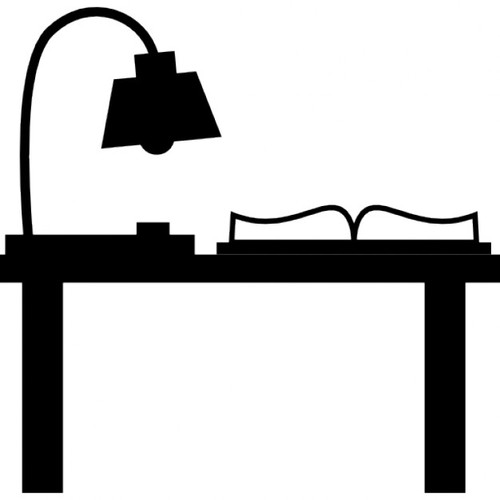ادب و افسانہ
میری موت
کہانی کی کہانی
یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ اس کہانی کا خاص کردار ایک فرقہ پرست مسلمان ہے۔ وہ مسلمان سكھوں سے ڈرتا ہے اور ان سے نفرت بھی کرتا ہے۔ وہ اپنے پڑوسی سكھ پر ذرا بھی بھروسا نہیں کرتا۔ تقسیم کے وقت جب فسادات ہوتے ہیں تب وہی پڑوسی سكھ اس مسلمان کو بچاتا ہے۔
لوگ سمجھتے ہیں کہ سردارجی مارے گئے۔ نہیں۔ یہ میری موت ہے۔ پرانے ’’میں‘‘ کی موت۔ میرے تعصبات کی موت۔ اس منافرت کی موت جو میرے دل میں تھی۔ میری یہ موت کیسے ہوئی؟ یہ بتانے کے لیے مجھے اپنے پرانے مردہ ’’میں‘‘ کو زندہ کرنا پڑےگا۔
میرا نام شیخ برہان الدین ہے۔ جب دہلی اور نئی دہلی میں فرقہ وارانہ قتل و غارت کا بازار گرم اور مسلمان کا خون سستا ہو گیا تو میں نے سوچا واہ ری قسمت۔ پڑوسی بھی ملا تو سکھ۔ حق ہمسائیگی ادا کرنا اور جان بچانا تو کجا، نہ جانے کب کر پان بھونک دے۔ بات یہ ہے کہ اس وقت تک میں سکھوں پر ہنستا بھی تھا۔ ان سے ڈرتا بھی تھا اور کافی نفرت بھی کرتا تھا۔ آج سے نہیں بچپن سے۔ میں شاید چھ برس کا تھا جب پہلی بار میں نے ایک سکھ کو دیکھا تھا جو دھوپ میں بیٹھا اپنے بالوں میں کنگھی کر رہا تھا۔ میں چلا پڑا، ’’ارے وہ دیکھو، عور ت کے منہ پرکتنی لمبی داڑھی!‘‘ جیسے جیسے عمر گزرتی گئی، یہ استعجاب ایک نسلی نفرت میں تبدیل ہوتا گیا۔ گھر کی بڑی بوڑھیاں جب کسی بچے کے بارے میں نامبارک بات کا ذکر کرتیں۔ مثلاً یہ کہ اسے نمونیہ ہو گیا تھا، یا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی تو کہتیں، ’’اب سے دور کسی سکھ فرنگی کو نمونیہ ہو گیا تھا یا اب سے دور کسی سکھ فرنگی کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ بعد کو معلوم ہوا کہ یہ کو سنا ۱۸۵۷ء کی یادگار تھا۔ جب ہندو مسلمانوں کی جنگ آزادی کو دبانے میں پنجاب کے سکھ راجوں اور ان کی فوجوں نے فرنگیوں کا ساتھ دیا تھا۔ مگر اس وقت تاریخی حقائق پر نظر نہیں تھی، صرف ایک مبہم سا خوف، ایک عجیب سی نفرت اور ایک عمیق تعصب۔ ڈر انگریز سے بھی لگتا تھا اور سکھ سے بھی، مگر انگریز سے زیادہ۔
مثلاً جب میں کوئی دس برس کا تھا، ایک روز دہلی سے علی گڑھ جا رہا تھا۔ ہمیشہ تھرڈ یا انٹر میں سفر ہوتا تھا۔ سوچا کہ اب کی بار سیکنڈ کلاس میں سفر کرکے دیکھا جائے۔ ٹکٹ خرید لیا اور ایک خالی ڈبے میں بیٹھ کر گدوں پر خوب کودا، باتھ روم کے آئینے میں اُچک اچک کر اپنا عکس دیکھا۔ سب پنکھوں کو ایک ساتھ چلا دیا۔ روشنیوں کو کبھی جلایا کبھی بجھایا۔ مگر ابھی گاڑی کے چلنے میں دو تین منٹ باقی تھے کہ لال لال منھ والے چار فوجی گورے آپس میں ڈیم بلاڈی قسم کی گفتگو کرتے ہوئے درجے میں گھس آئے۔ ان کو دیکھنا تھا کہ سیکنڈ کلاس میں سفر کرنے کا شوق رفوچکر ہو گیا اور اپنا سوٹ کیس گھسیٹتا میں بھاگا اور ایک نہایت کچھا کھچ بھرے ہوئے تھرڈ کلاس کے ڈبے میں آکر دم لیا۔ یہاں دیکھا کہ کئی سکھ داڑھیاں کھولے، کچھے پہنے بیٹھے تھے مگر میں ان سے ڈر کر درجہ چھوڑ کر نہیں بھاگا۔ صرف ان سے ذرا فاصلے پر بیٹھ گیا۔
ہاں، تو ڈر سکھوں سے بھی لگتا تھا اور انگریزوں سے ان سے زیادہ۔ مگر انگریز انگریز تھے اور کوٹ پتلون پہنتے تھے جو میں بھی پہننا چاہتا تھا اور ڈیم بلاڈی فول والی زبان بولتے تھے جو میں بھی سیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ حاکم تھے اور میں بھی چھوٹا موٹا حاکم بننا چاہتا تھا۔ وہ کانٹے کی چھری سے کھانا کھاتے تھے اور میں بھی کانٹے چھری سے کھانا کھانے کا خواہاں تھا تاکہ دنیا مجھے بھی مہذب اور متمدن سمجھے مگر سکھوں سے جو ڈر لگتا تھا، وہ حقارت آمیز۔ کتنے عجیب الخلقت تھے یہ سکھ جو مرد ہو کر بھی سر کے بال عورتوں کی طرح لمبے لمبے رکھتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ انگریزی فیشن کی نقل میں سر کے بال منڈانا کچھ مجھے بھی پسند نہیں تھا۔ ابا کے اس حکم کے باوجود کہ ہر جمعہ کو سر کے بال خشخشی کرائے جائیں، میں نے بال خوب بڑھا رکھے تھے، تاکہ ہاکی اور فٹ بال کھیلتے وقت بال ہوا میں اڑیں جیسے انگریزی کھلاڑیوں کے۔
ابا کہتے، ’’یہ کیا عورتوں کی طرح پٹے بڑھا رکھے ہیں مگر ابا تو تھے ہی پرانے دقیانوسی خیال کے۔ ان کی بات کون سنتا تھا۔ ان کابس چلتا تو سر پر استرا چلوا کر بچپن میں بھی ہمارے چہروں پر داڑھیاں بندھوا دیتے۔۔۔ ہاں اس پر یاد آیا کہ سکھوں کے عجیب الخلقت ہونے کی دوسری نشانی ان کی داڑھیاں تھیں اور پھر داڑھی، داڑھی میں بھی فرق ہوتا ہے۔ مثلاً ابا کی داڑھی جس کو نہایت اہتمام سے نائی فرنچ کٹ بنایا کرتا تھا یا تایا ابا کی جو نکیلی اور چونچ دار تھی۔ مگر یہ بھی کیا کہ داڑھی کو کبھی قینچی لگے ہی نہیں۔ جھاڑ جھنکار کی طرح بڑھتی ہی رہے بلکہ تیل اور دہی اور نہ جانے کیا کیا مل کر بڑھائی جائے اور جب کئی فٹ لمبی ہو جائے تو اس میں کنگھی کی جائے جیسے عورتیں سر کے بالوں میں کرتی ہیں۔۔۔ عورتیں یا مجھ جیسے اسکول کے فیشن ایبل لڑکے۔ اس کے علاوہ دادا جان کی داڑھی بھی کئی فٹ لمبی تھی اور وہ بھی اس میں کنگھی کرتے تھے۔ مگر دادا جان کی بات اور تھی۔ آخر وہ۔۔۔ میرے داداجان ٹھیرے اور سکھ پھر سکھ تھے۔
میٹرک کرنے کے بعد مجھے پڑھنے لکھنے کے لیے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ بھیجا گیا۔ کالج میں جو پنجابی لڑکے پڑھتے تھے، ان کو ہم دہلی اور یوپی والے نیچ، جاہل اور اجڈ سمجھتے تھے۔ نہ بات کرنے کا سلیقہ نہ کھانے پینے کی تمیز۔ تہذیب و تمدن چھو نہیں گئے تھے۔ گنوار، لٹھ۔ یہ بڑے بڑے لسی کے گلاس پینے والے بھلا کیوڑے دار فالودے اور لپٹن کی چائے کی لذت کیا جانیں۔ زبان نہایت ناشائستہ۔ بات کریں تو معلوم ہو لڑ رہے ہیں۔ اسی، لسی، ساڈے، تہاڈے۔۔۔ لاحول ولاقوۃ۔ میں تو ہمیشہ ان پنجابیوں سے کترا تاتھا مگر خدا بھلا کرے ہمارے وارڈن صاحب کا کہ انہوں نے ایک پنجابی کو میرے کمرے میں جگہ دے دی۔ میں نے سوچا چلو جب ساتھ ہی رہنا ہے تو تھوڑی بہت حدتک دوستی ہی کرلی جائے۔ کچھ دنوں میں کافی گاڑھی چھننے لگی۔ اس کا نام غلام رسول تھا۔ راولپنڈی کا رہنے والا تھا۔ کافی مزے دار آدمی تھا اور لطیفے خوب سنایا کرتا تھا۔
اب آپ کہیں گے ذکر شروع ہوا تھا سردار صاحب کا۔ یہ غلام رسول کہاں سے ٹپک پڑا۔ مگر اصل میں غلام رسول کا اس قصے سے قریبی تعلق ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ جو لطیفے سناتا تھا وہ عام طور سے سکھوں کے بارے میں ہوتے تھے جن کو سن سن کر مجھے پوری سکھ قوم کی عادات و خصائص، ان کی نسلی خصوصیات اور اجتماعی کیریکٹر کا بخوبی علم ہو گیا تھا۔ بقول غلام رسول کے، سکھ تمام بیوقوف اور بدھو ہوتے ہیں۔ بارہ بجے تو ان کی عقل بالکل خبط ہو جاتی ہے۔ اس کے ثبوت میں کتنے ہی واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں۔ مثلاً ایک سردار جی دن کے بارہ بجے سائیکل پر سوار امرت سر کے ہال بازار سے گزر رہے تھے۔ چوراہے پر ایک سکھ کانسٹبل نے روکا اور پوچھا، ’’تمہاری سائیکل کی لائٹ کہاں ہے؟‘‘ سائیکل سوار سردارجی گڑگڑا کر بولے، ’’جمعدار صاحب ابھی ابھی بجھ گئی ہے گھر سے جلاکر تو چلا تھا۔‘‘ اس پر سپاہی نے چالان کرنے کی دھمکی دی۔ ایک راہ چلتے سفید داڑھی والے سردار جی نے بیچ بچاؤ کرایا، ’’چلو بھئی کوئی بات نہیں۔ لائٹ بجھ گئی ہے تو اب جلا لو۔‘‘ اور اسی قسم کے سیکڑوں قصے غلام رسول کو یاد تھے اور انہیں جب وہ پنجابی مکالموں کے ساتھ سناتا تھا تو سننے والوں کے پیٹ میں بل پڑجاتے تھے۔ اصل میں ان کو سننے کا مزہ پنجابی ہی میں تھا کیونکہ اجڈ سکھوں کی عجیب و غریب حرکتوں کے بیان کرنے کا حق کچھ پنجابی جیسی اجڈ زبان ہی میں ہو سکتا ہے۔ سکھ نہ صرف بیوقوف اور بدھو تھے بلکہ گندے تھے جیسا کہ ایک ثبوت تو غلام رسول کا (جس نے سیکڑوں سکھوں کو دیکھا تھا) یہ تھا کہ وہ بال نہیں منڈاتے تھے۔ اس کے برخلاف ہم صاف ستھرے نمازی مسلمانوں کے جوہر اٹھوارے جمعہ کے جمعہ غسل کرتے ہیں، یہ سکھ کچھ باندھ سب کے سامنے نل کے نیچے بیٹھ کر نہاتے تو روز ہیں مگر اپنے بالوں اور داڑھی میں نہ جانے کیا کیا گندی اور غلیظ چیزیں ملتے ہیں۔ مثلاً دہی۔ ویسے تو میں بھی سر میں لائم جیوس گلیسرین لگاتا ہوں جو کسی قدر گاڑھے گاڑھے دودھ سے مشابہ ہوتی ہے مگر اس کی بات اور ہے۔ وہ ولایت کی مشہور پرفیومر فیکٹری سے نہایت خوبصورت شیشی میں آتی ہے اور دہی کسی گندے سندے حلوائی کی دکان سے۔ خیر جی ہمیں دوسروں کے رہنے سہنے کے طریقوں سے کیا لینا۔ مگر سکھوں کا سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ یہ لوگ اکھڑپن، بدتمیزی اور ماردھاڑ میں مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی جرأت کرتے تھے۔ اب دنیا جانتی ہے کہ ایک اکیلا مسلمان دس ہندوؤں یا سکھوں پر بھاری ہوتا ہے۔ مگر پھر یہ سکھ مسلمانوں کے رعب کو نہیں مانتے تھے۔ کرپانیں لٹکائے، اکڑ اکڑ کر مونچھوں بلکہ داڑھی پر بھی تاؤ دیتے چلتے تھے۔ غلام رسول کہتا ان کی ہیکڑی ایک دن ہم ایسی نکالیں گے کہ خالصہ جی یاد ہی تو کریں گے۔
کالج چھوڑے کئی سال گزر گئے۔ طالب علم سے میں کلرک اور کلرک سے ہیڈ کلرک بن گیا۔ علی گڑھ کا ہوسٹل چھوڑ نئی دہلی میں ایک سرکاری کوارٹر میں رہنا سہنا اختیار کر لیا۔ شادی ہو گئی۔ بچے ہو گئے، مگر کتنی ہی مدت کے بعد مجھے غلام رسول کا وہ کہنا یاد آیا۔ جب ایک سردار صاحب میرے برابر کے کوارٹر میں رہنے کو آئے۔۔۔ یہ راولپنڈی سے بدلی کراکر آئے تھے کیونکہ راولپنڈی کے ضلع میں غلام رسول کی پیشن گوئی کے بموجب سرداروں کی ہیکڑی اچھی طرح سے نکالی گئی تھی۔ مجاہدوں نے ان کا صفایا کر دیا تھا۔ بڑے سورما بنتے تھے، کرپانیں لیے پھرتے تھے۔ بہادر مسلمانوں کے سامنے ان کی ایک نہ بنی۔ ان کی داڑھیاں مونڈ کر ان کو مسلمان بنایا گیا تھا۔ زبردستی ان کا ختنہ کیا گیا تھا۔ ہندو پریس حسب عادت مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے یہ لکھ رہا تھا کہ سکھ عورتوں اور بچوں کو بھی مسلمانوں نے قتل کیا ہے۔ حالانکہ یہ اسلامی روایات کے خلاف ہے۔ کوئی مسلمان مجاہد کبھی عورت یا بچے پر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ رہیں عورتوں اور بچوں کی لاشوں کی تصویریں جو چھاپی جا رہی تھیں، وہ یا تو جعلی تھیں اور یا سکھوں نے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے خود اپنی عورتوں اور بچوں کو قتل کیا ہوگا۔ راولپنڈی اور مغربی پنجاب کے مسلمانوں پر یہ بھی الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے ہندو اور سکھ لڑکیوں کو بھگایا تھا، حالانکہ واقعہ صرف اتنا ہے کہ مسلمانوں کی جواں مردی کی دھاک بیٹھی ہے اور اگر نوجوان مسلمانوں پر ہندو اور سکھ لڑکیاں خود ہی لٹو ہو جائیں تو ان کا کیا قصور ہے کہ وہ تبلیغ اسلام کے سلسلے میں ان لڑکیوں کو اپنی پناہ میں لے لیں۔ ہاں تو سکھوں کی نام نہاد بہادری کا بھانڈا پھوٹ گیا تھا۔ بھلا اب تو ماسٹر تارا سنگھ لاہور میں کرپان نکال کر مسلمانوں کو دھمکیاں دے۔ پنڈی سے بھاگے ہوئے سردار اور اس کی خستہ حالی کو دیکھ کر میرا سینہ عظمت اسلام کی روح سے بھر گیا۔
ہمارے پڑوسی سردار جی کی عمر کوئی ساٹھ برس کی ہو گئی۔ داڑھی بالکل سفید ہو چکی تھی، حالانکہ موت کے منہ سے بچ کر آئے تھے۔ مگر یہ حضرت ہر وقت دانت نکالے ہنستے رہتے تھے، جس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ دراصل کتنا بیوقوف اور بے حس ہے۔ شروع شروع میں انہوں نے مجھے اپنی دوستی کے جال میں پھنسانا چاہا۔ آتے جاتے زبردستی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ نہ جانے سکھو ں کا کون سا تہوار تھا، اس دن پرشاد کی مٹھائی بھی بھیجی (جو میری بیوی نے فوراً مہترانی کو دے دی) پر میں نے زیادہ منھ نہ لگایا۔ کوئی بات ہوئی سوکھا سا جواب دے دیا اور بس۔ میں جانتا تھا کہ سیدھے منہ دو چار باتیں کرلیں تو یہ پیچھے ہی پڑ جائےگا۔ آج باتیں تو کل گالم گفتار۔ گالیاں تو آپ جانتے ہی ہیں، سکھوں کی دال روٹی ہوتی ہے۔ کون اپنی زبان گندی کرے ایسے لوگوں سے تعلقات بڑھاکر۔ ہاں ایک اتوار کی دوپہر کو میں اپنی بیوی کو سکھوں کی حماقت کے قصے سنا رہا تھا۔ اس کا عملی ثبوت دینے کے لیے عین بارہ بجے میں نے اپنے نوکر کو سردار جی کے ہاں بھیجا کہ پوچھ کر آئے کیا بجا ہے؟ انہوں نے کہلوا دیا، بارہ بج کر دو منٹ ہوئے ہیں۔ میں نے کہا، ’’بارہ بجے کا نام لیتے گھبراتے ہیں یہ۔‘‘ اور ہم خوب ہنسے۔ اس کے بعد میں نے کئی بار بےوقوف بنانے کے لیے سردارجی سے پوچھا، ’’کیوں سردارجی! بارہ بج گئے؟‘‘ اور وہ بےشرمی سے دانت پھاڑ کر جواب دیتے، ’’جی اساں دے تاں چوبیس گھنٹے بارہ بجے رہتے ہیں۔‘‘ اور یہ کہہ کر خوب ہنسے۔ گویا یہ بڑا مذاق ہوا۔ مجھے سب سے زیادہ ڈر بچوں کی طرف سے تھا۔ اول تو کسی سکھ کا اعتبار نہیں۔ کب بچے ہی کے گلے پر کرپان چلا دے۔ پھر یہ لوگ راولپنڈی سے آئے تھے۔ ضرور دل میں مسلمانوں کی طرف سے کینہ رکھتے ہوں گے اور انتقام لینے کی تاک میں ہوں گے۔ میں نے بیوی کو تاکید کر دی تھی کہ بچے ہرگز سردار جی کے کوارٹر کی طرف نہ جانے دیے جائیں۔ پربچے تو بچے ہی ہوتے ہیں۔ چند روز بعد میں نے دیکھا کہ سردار کی چھوٹی لڑکی موہنی اور ان کے پوتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ یہ بچی جس کی عمر مشکل سے دس برس کی ہوگی، سچ مچ موہنی ہی تھی۔ گوری چٹی، اچھا ناک نقشہ، بڑی خوبصورت۔ کمبختوں کی عورتیں کافی خوبصورت ہوتی ہیں۔ مجھے یاد آیا کہ غلام رسول کہا کرتا تھا کہ اگر پنجاب سے سکھ مرد چلے جائیں اور اپنی عورتوں کو چھوڑ جائیں تو پھر حوروں کی تلاش کی ضرورت نہیں۔ ہاں تو جب میں نے بچوں کو سردارجی کے بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھا تو میں ان کو گھسیٹتا ہوا اندر لے آیا اور خوب پٹائی کی۔ پھر میرے سامنے کم سے کم ان کی ہمت نہ ہوئی کہ ادھر کا رخ کریں۔
بہت جلد سکھوں کی اصلیت پوری طرح ظاہر ہو گئی۔ راولپنڈی سے تو ڈرپوکوں کی طرح پٹ کر بھاگ کر آئے تھے۔ پر مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کو اقلیت میں پاکر ان پر ظلم ڈھانا شروع کر دیا۔ ہزاروں بلکہ لاکھوں مسلمانوں کو جامِ شہادت پینا پڑا۔ اسلامی خون کی ندیاں بہہ گئیں۔ ہزاروں عورتوں کو برہنہ کرکے جلوس نکالا گیا۔ جب سے مغربی پنجاب سے بھاگے ہوئے سکھ اتنی بڑی تعداد میں دہلی میں آنے شروع ہوئے تھے، اس وبا کا یہاں تک پہنچنا یقینی ہو گیا تھا۔ میرے پاکستان جانے میں ابھی چند ہفتے کی دیر تھی۔ اس لیے میں نے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کو ہوائی جہاز سے کراچی بھیج دیا اور خود خدا پر بھروسہ کرکے ٹھہرا رہا۔ ہوائی جہاز میں سامان تو زیادہ نہیں جا سکتا تھا، اس لیے میں نے پوری ایک ویگن بک کرا لی مگر جس دن سامان چڑھانے والے تھے اس دن سنا کہ پاکستان جانے والی گاڑیوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ اس لیے سامان گھر میں ہی پڑا رہا۔
۱۵ اگست کو آزادی کا جشن منایا گیا مگر مجھے اس آزادی میں کیا دلچسپی تھی۔ میں نے چھٹی منائی، اور دن بھر لیٹا ڈان اور پاکستان ٹائمز کا مطالعہ کرتا رہا۔ دونوں میں نام نہاد۔۔۔ آزادی کے چیتھڑے اڑائے گئے تھے اور ثابت کیا گیا تھا کہ کس طرح ہندوؤں اور انگریزوں نے مل کر مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کی سازش کی تھی۔ وہ تو ہمارے قائد اعظم کا اعجاز تھا کہ پاکستان لے کر ہی رہے۔ اگرچہ انگریزوں نے ہندوؤں اور سکھوں کے دباؤ میں آکر امرتسر کو ہندوستان کے حوالے کر دیا۔ حالانکہ دنیا جانتی ہے، امرت سر خالص اسلامی شہر ہے اور یہاں کی سنہری مسجد جو (GOLDEN MOSQUE) کے نام سے دنیا میں مشہور ہے۔۔۔ نہیں وہ تو گرودوارہ ہے اور (GOLDEN TEMPLE) کہلاتا ہے۔ سنہری مسجد تو دہلی میں ہے۔ سنہری مسجد ہی نہیں، جامع مسجد بھی۔ لال قلعہ ہے، نظام الدین اولیا کا مزار، ہمایوں کا مقبرہ، صفدر جنگ کا مدرسہ۔ غرض کہ چپے چپے پر اسلامی حکومت کے نشان پائے جاتے ہیں۔ پھر بھی آج اسی دہلی بلکہ کہنا چاہیے کہ شاہ جہان آباد پر ہندو سامراج کا جھنڈا بلند کیا جا رہا تھا۔۔۔ رولے اب دل کھول کے اے دیدہ خونبار۔۔۔ اور یہ سوچ کر میرا دل بھر آیا کہ دہلی جو کبھی مسلمانوں کا پایۂ تخت تھا، تہذیب و تمدن کا گہوارہ تھا، ہم سے چھین لیا گیا تھا اور ہمیں مغربی پنجاب اور سندھ بلوچستان جیسے اجڈ اور غیرمتمدن علاقے میں زبردستی بھیجا جا رہا ہے۔ جہاں کسی کو شستہ اردو زبان بھی بولنی نہیں آتی۔ جہاں شلوار جیسا مضحکہ خیز لباس پہنا جاتا ہے۔ جہاں ہلکی پھلکی پاؤ بھر میں بیس چپاتیوں کی بجائے دو دو سیر کی نانیں کھائی جاتی ہیں۔ پھر میں نے اپنے دل کو مضبوط کرکےكہا كہ قائد اعظم اور پاکستان کی خاطر یہ قربانی تو ہمیں دینی ہی ہوگی، مگر پھر بھی دلی چھوڑنے کے خیال سے دل مرجھایا ہی رہا۔۔۔ شام کو جب میں باہر نکلا اور سردار جی نے دانت نکال کر کہا، ’’کیوں بابو جی! تم نے آج کچھ کھشی نہیں منائی؟‘‘ تو میرے جی میں آئی کہ اس کی داڑھی میں آگ لگادوں۔ ہندوستان کی آزادی اور دل میں سِکھا شاہی آخر رنگ لا کر ہی رہی۔ اب مغربی پنجاب سے آئے ہوئے رفیوجیز (REFUGEES) کی تعداد ہزاروں سے لاکھوں تک پہنچ گئی۔ یہ لوگ دراصل پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کر، وہاں سے بھاگے تھے۔ یہاں آکر گلی کوچوں میں اپنا رونا روتے پھرتے تھے۔ کانگریسی پروپیگنڈا مسلمانوں کے خلاف زوروں پر چل رہا تھا اور اس بار کانگریسیوں نے چال یہ چلی کہ بجائے کانگریس کے نام لینے کے، راشٹریہ سیوک سنگھ اور شہیدی دل کے نام سے کام کر رہے تھے۔ حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ یہ ہندو چاہے کانگریسی ہوں یا مہاسبھائی، سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ چاہے دنیا کو دکھانے کی خاطر وہ بظاہر گاندھی اور جواہر لال نہرو کو گالیاں ہی کیوں نہ دیتے ہوں۔
ایک دن صبح کو خبر آئی کہ دہلی میں قتل عام شروع ہو گیا۔ قرول باغ میں مسلمانوں کے سیکڑوں گھر پھونک دیے گئے۔ چاندنی چوک کے مسلمانوں کی دوکانیں لوٹ لی گئیں اور ہزاروں کا صفایا ہو گیا۔ یہ تھا کانگریس کے ہندوراج کا نمونہ۔ خیرمیں نے سوچا نئی دہلی تو مدت سے انگریزوں کا شہر رہا ہے۔ لارڈ ماونٹ بیٹن یہاں رہتے ہیں۔ کمانڈر ان چیف یہاں رہتا ہے۔ کم سے کم یہاں وہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا ظلم نہ ہونے دیں گے۔ یہ سوچ کر میں دفتر کی طرف چلا۔ کیونکہ اس دن مجھے پراويڈنٹ فنڈ کا حساب کرنا تھا اور دراصل اسی لیے میں نے پاکستان جانے میں دیر کی تھی۔ ابھی گول مارکیٹ کے پاس پہنچا ہی تھا کہ دفتر کا ایک ہندو بابو ملا۔ اس نے کہا، ’’یہ کیا کر رہے ہو۔ جاؤ واپس جاؤ۔ باہر نہ نکلنا۔ کناٹ پلیس میں بلوائی مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔‘‘ میں واپس بھاگ آیا۔ اپنے اسکوائر میں پہنچا ہی تھا کہ سردار جی سے مڈبھیڑ ہو گئی۔ کہنے لگے، ’’شیخ جی فکر نہ کرنا۔ جب تک ہم سلامت ہیں تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔‘‘ میں نے سوچا اس کی داڑھی کے پیچھے کتنا مکر چھپا ہوا ہے۔ دل میں تو خوش ہے۔ چلو اچھا ہوا مسلمانوں کا صفایا ہو رہا ہے۔۔۔ مگر زبانی ہمدردی جتا کر مجھ پر احسان کر رہا ہے بلکہ شاید مجھے چڑانے کے لیے یہ کہہ رہا ہے۔ کیونکہ سارے اسکوائر میں بلکہ تمام سڑک پر میں تن تنہا مسلمان تھا۔ پر مجھے ان کافروں کا رحم و کرم نہیں چاہیے۔ میں سوچ کر اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ میں مارا بھی جاؤں گا تو دس بیس کو مار کر۔ سیدھا اپنے کمرے میں گیا جہاں پلنگ کے نیچے، میری دونالی شکاری بندوق رکھی تھی۔ جب سے فسادات شروع ہوئے تھے، میں نے کارتوس اور گولیوں کا بھی کافی ذخیرہ جمع کر رکھا تھا۔ پر وہاں بندوق نہ ملی۔ سارا گھر چھان مارا۔ اس کا کہیں پتہ نہ چلا۔ ’’کیوں حضور! کیا ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟‘‘ ’’یہ میرا وفادار ملازم ممدو تھا۔‘‘ ’’میری بندوق کیا ہوئی؟‘‘ میں نے پوچھا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ مگر اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ اسے معلوم ہے۔ شاید اس نے چھپائی ہے، یا چرائی ہے۔ ’’بولتا کیوں نہیں؟‘‘ میں نے ڈانٹ کر کہا۔ تب حقیقت معلوم ہوئی کہ ممدو نے میری بندوق چرا کر اپنے چند دوستوں کو دے دی تھی، جو دریاگنج میں مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ہتھیاروں کا ذخیرہ جمع کر رہے تھے۔ ’’کئی سو بندوقیں ہیں سرکار ہمارے پاس۔ سات مشین گنیں، دس ریوالور اور ایک توپ۔ کافروں کو بھون کر رکھ دیں گے۔ بھون کر۔‘‘ میں نے کہا، ’’دریاگنج میں میری بندوق سے کافروں کو بھون دیا گیا تو اس میں میری حفاظت کیسے ہوگی۔ میں تو یہاں نہتا کافروں کے نرغے میں پھنسا ہوا ہوں۔ یہاں مجھے بھون دیا گیا تو کون ذمےدار ہوگا؟‘‘ میں نے ممدو سے کہا وہ کسی طرح چھپتا چھپاتا دریاگنج تک جائے اور وہاں سے میری بندوق اور سو دو سو کارتوس لے کر آئے۔ وہ چلا تو گیا مگر مجھے یقین تھا کہ اب وہ لوٹ کر نہیں آئےگا۔ اب میں گھر میں بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ سامنے کارنس پر میری بیوی اور بچوں کی تصویریں خاموشی سے مجھے گھور رہی تھیں۔ یہ سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو آگئے کہ اب ان سے کبھی ملاقات ہوگی بھی یا نہیں لیکن پھر یہ خیال کر کے اطمینان بھی ہوا کہ کم سے کم وہ تو خیریت سے پاکستان پہنچ گئے تھے۔ کاش میں نے پراويڈنٹ فنڈ کا لالچ نہ کیا ہوتا اور پہلے ہی چلا گیا ہوتا۔ پر اب پچھتانے سے کیا ہوتا ہے۔۔۔
’’ست سری اکال۔۔۔ ہر ہر مہادیو۔‘‘ دور سے آوازیں قریب آرہی تھیں۔ یہ بلوائی تھے۔ یہ میری موت کے ہرکارے تھے۔ میں نے زخمی ہرن کی طرح ادھر ادھر دیکھا، جو گولی کھا چکا ہو اور جس کے پیچھے شکاری کتے لگے ہوں۔ بچاؤ کی کوئی صورت نہ تھی۔ کوارٹر کے کواڑ پتلی لکڑی کے تھے اور ان میں شیشے لگے ہوئے تھے۔ اگر میں بند ہوکر بیٹھ بھی رہا تو دومنٹ میں بلوائی کواڑ توڑ کر اندر آ سکتے تھے۔
’’ست سری اکال۔ ہر ہر مہادیو۔‘‘ آوازیں اور قریب آرہی تھیں۔ میری موت قریب آ رہی تھی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ سردارجی داخل ہوئے، ’’شیخ جی! تم ہمارے کوارٹر میں آ جاؤ۔ جلدی کرو۔‘‘ بغیر سوچے سمجھے اگلے لمحے میں سردار جی کے برآمدے کی چکوں کے پیچھے تھا۔ موت کی گولی سن سے میرے سر پر سے گزر گئی۔ کیونکہ میں وہاں داخل ہی ہوا تھا کہ ایک لاری آ کر رکی اور اس میں سے دس پندرہ نوجوان اترے۔ ان کے لیڈر کے ہاتھ میں ایک ٹائپ کی ہوئی فہرست تھی۔ کوارٹر ۸ شیخ برہان الدین۔ اس نے کاغذ پر نظر ڈالتے ہوئے حکم دیا اور یہ غول کا غول میرے کوارٹر پر ٹوٹ پڑا۔ میری گرہستی کی دنیا میری آنکھوں کے سامنے اجڑ گئی۔ لٹ گئی۔ کرسیاں، میزیں، صندوق، تصویر، کتابیں، دریاں، قالین، یہاں تک کہ میلے کپڑے ہر چیز لاری پر پہنچا دی گئی۔ ڈاکو! لٹیرے! قزاق!
اور یہ سردارجی جو بظاہر ہمدردی جتاکر مجھے یہاں لے آئے تھے۔ یہ کون سے کم لٹیرے تھے؟ باہر جا کر بلوائیوں سے کہنے لگے، ’’ٹھہریے صاحب۔ اس گھر پر ہمارا حق زیادہ ہے۔ ہمیں بھی اس لوٹ میں حصہ ملنا چاہیے اور یہ کہہ کر انہوں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو اشارہ کیا اور وہ بھی لوٹ میں شامل ہو گئے۔ کوئی میری پتلون اٹھائے چلا آ رہا ہے۔ کوٹ سوٹ کیس، کوئی میری بیوی بچوں کی تصویریں بھی لا رہا ہے اور یہ سب مال غنیمت سیدھا اندر کے کمرے میں جا رہا تھا۔‘‘ اچھا رے سردار! زندہ رہا تو تجھ سے بھی سمجھوں گا۔ پر اس وقت تو میں چوں بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ فسادی جو سب کے سب مسلح تھے، مجھ سے چند گز کے فاصلے پر تھے۔ اگر انہیں کہیں معلوم ہو گیا کہ میں یہاں ہوں۔۔۔ ’’ارے اندر آؤ توسی!‘‘ دفعتاً میں نے دیکھا کہ سردارجی ننگی کرپان ہاتھ میں لیے مجھے اندر بلا رہے ہیں۔ میں نے ایک بار اس دڑھیل چہرے کو دیکھا جو لوٹ مارکی بھاگ دوڑ سے اور بھی خوفناک ہو گیا تھا اور پھر کرپان کو جس کی چمکیلی دھار مجھے دعوتِ موت دے رہی تھی، بحث کرنے کا موقع نہیں تھا۔ اگر میں کچھ بھی بولا اور بلوائیوں نے سن لیا تو ایک گولی میرے سینے کے پار ہوگی۔ کرپان اور بندوق میں سے ایک کو پسند کرنا تھا۔ میں نے سوچا ان دس بندوق باز بلوائیوں سے کرپان والا بڈھا بہتر ہے۔ میں کمرے میں چلا گیا۔۔۔ جھجکتا ہوا خاموش۔ ’’اتھے نہیں۔ اوس اندر آؤ۔‘‘ میں اور اندر کے کمرے میں چلا گیا، جیسے بکرا قصائی کے ساتھ ذبح خانے میں داخل ہوتا ہے۔ میری آنکھیں کرپان کی دھار سے چوندھیاتی جا رہی تھی۔
’’یہ لو جی۔ اپنی چیزیں سنبھال لو۔‘‘ یہ کہہ کر سردار جی نے وہ تمام سامان میرے سامنے رکھ دیا جو انہوں نے اور ان کے بچوں نے جھوٹ موٹ کی لوٹ میں حاصل کیا تھا۔ سردارنی بولی، ’’بیٹا ہم تو تیرا کچھ بھی سامان نہ بچا سکے۔‘‘ میں کوئی جواب نہ دے سکا۔ اتنے میں باہر سے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ بلوائی میری لوہے کی الماری کو باہر نکال رہے تھے اور اس کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کی چابیاں مل جاتیں تو سب معاملہ آسان ہو جاتا۔ ’’چابیاں تو اس کی پاکستان میں ملیں گی۔ بھاگ گیا نا ڈرپوک کہیں کا۔ مسلمان کا بچہ تھا تو مقابلہ کرتا۔۔۔‘‘ ننھی موہنی میری بیوی کے چند ریشمی قمیص اور غرارے نہ جانے کس سے چھین کر لا رہی تھی کہ اس نے یہ سنا۔ وہ بولی، ’’تم بڑے بہادر ہو! شیخ جی ڈرپوک کیوں ہونے لگے۔ وہ تو کوئی بھی پاکستان نہیں گئے۔‘‘ ’’نہیں گیا تو یہاں سے کہیں منھ کالا کر گیا۔‘‘ ’’منہ کالا کیوں کرتے وہ تو ہمارے ہاں۔۔۔‘‘ میرے دل کی حرکت ایک لمحے کے لیے بند ہو گئی۔ بچی اپنی غلطی کا احساس کرتے ہی خاموش ہو گئی۔ مگر ان بلوائیوں کے لیے یہی کافی تھا۔ سردار جی پر جیسے خون سوار ہو گیا۔ انہوں نے مجھے اندر کے کمرے میں بند کرکے کنڈی لگا دی۔ اپنے بیٹے کے ہاتھ میں کرپان دی اور خود باہر نکل گئے۔ باہر کیا ہوا یہ مجھے ٹھیک طرح معلوم نہ ہوا۔ تھپڑوں کی آواز۔۔۔ پھر موہنی کے رونے کی آواز اور اس کے بعد سردار جی کی آواز۔ پنجابی گالیاں کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کسے گالیاں دے رہے ہیں اور کیوں۔ میں چاروں طرف سے بند تھا۔ اس لیے ٹھیک سنائی نہ دیتا تھا۔ اور پھر۔۔۔ گولی چلنے کی آواز۔۔۔ سردارنی کی چیخ۔۔۔ لاری روانہ ہونے کی گڑگڑاہٹ اور پھر تمام اسکوائر پر جیسے سناٹا چھا گیا۔ جب مجھے کمرے کی قید سے نکالا گیا تو سردارجی پلنگ پر پڑے تھے اور ان کے سینے کے قریب، سفید قمیص خون سے سرخ ہو رہی تھی۔ ان کا لڑکا ہمسائے کے گھر سے ڈاکٹر کو ٹیلیفون کر رہا تھا۔
’’سردار جی! یہ تم نے کیا کیا؟‘‘ میری زبان سے نہ جانے یہ الفاظ کیسے نکلے۔ میں مبہوت تھا۔۔۔ میری برسوں کی دنیا، خیالات، محسوسات، تعصبات کی دنیا کھنڈر ہو گئی تھی۔ ’’سردارجی یہ تم نے کیا کیا؟‘‘
’’مجھے کرجا اتارنا تھا بیٹا!‘‘ ’’قرضہ؟‘‘ ’’ہاں! راولپنڈی میں تمہارے جیسے ہی ایک مسلمان نے اپنی جان دے کر میری اور میرے گھر والوں کی جان اور اجت بچائی تھی۔‘‘ ’’کیا نام تھا اس کا سردارجی؟‘‘
’’گلام رسول!‘‘ ’’غلام رسول!‘‘ اور مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے میرے ساتھ قسمت نے دھوکہ کیا ہو۔ دیوار پر لٹکے ہوئے گھنٹے نے بارہ بجانے شروع کیے۔ ایک۔۔۔ دو۔۔۔ تین۔۔۔ چار۔۔۔ پانچ۔۔۔ سردارجی کی نگاہیں گھنٹے کی طرف پھر گئیں جیسے مسکرا رہے ہوں اور مجھے اپنے دادا یاد آ گئے جن کی کئی فٹ لمبی داڑھی تھی۔ سردار جی کی شکل ان سے کتنی ملتی تھی۔ چھ۔۔۔ سات۔۔۔ آٹھ۔۔۔ نو۔۔۔ جیسے وہ ہنس رہے ہوں، ان کی سفید داڑھی اور سر کے کھلے ہوئے بالوں نے چہرے کے گرد ایک نورانی ہالہ سا بنایا ہوا تھا۔۔۔ دس۔۔۔ گیارہ۔۔۔ بارہ۔۔۔ جیسے وہ کہہ رہے ہوں، ’’جی اساں دے ہاں تو چوبیس گھنٹے بارہ بجے رہتے ہیں۔‘‘ پھر وہ نگاہیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ اور میرے کانوں میں غلام رسول کی آواز دور سے، بہت دور سے آئی۔ میں کہتا نہ تھا کہ بارہ بجے ان سکھوں کی عقل غائب ہو جاتی ہے اور یہ کوئی نہ کوئی حماقت کر بیٹھتے ہیں۔ اب ان سردارجی ہی کو دیکھو۔۔۔ ایک مسلمان کی خاطر اپنی جان دے دی۔ پر یہ سردار جی نہیں مرے تھے۔ میں مرا تھا!