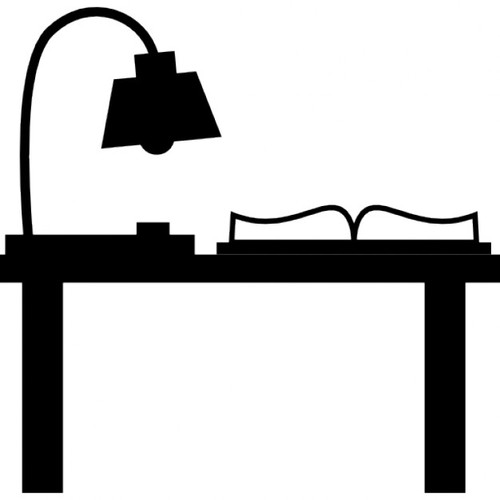لاہور رنگ روڈ ابھی تعمیر کے آخری مراحل میں ہے۔ ۸۰ فیصد سے زائد دائروی سڑک مکمل ہو چکی۔ شہر کے نئے ہوائی اڈے سے اس سڑک پر جنوب کی طرف چلتے جائیں تو چند کلومیٹر پر ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی واقع ہے۔ یہ اپنے اندازِ تعمیر میں ایک نیا لاہور ہے۔ خوبصورت، عالی شان کوٹھیاں، کشادہ سڑکیں، صاف ستھری اجلی فضا، سڑک کے ہر دو جوانب تراشیدہ سایہ دار درخت اور دو طرفہ سڑکوں کے کنارے کنارے ایستادہ گھر، جن کے باہر دس دس مربع فٹ کے گھاس کے کارپٹ بچھائے گئے ہیں۔ بڑے بڑے چمکیلے صدری دروازے جن کی اونچائی صرف اتنی ہے کہ باہر کھڑا اوسط قد کا آدمی بھی بآسانی پورچ میں دیکھ سکتا ہے۔یہ ساری کوٹھیاں قبرستان کی طرح خاموشی اوڑھے کھڑی ہیں۔ ان کے اندر کتنا شور ہے، ان کی خارجی ہیئت سے اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ البتہ ایک بات مسلمہ ہے کہ ان کوٹھیوں کے رہائشی بہت آرام اور سکون میں ہیں۔ کم از کم بظاہر تو یہی گمان گزرتا ہے۔ اگر آپ عین اْسی جگہ جہاں اس وقت میں کھڑی ہوں صرف ۱۰ منٹ کے لیے کھڑے ہوں تو اس مختصر عرصے میں اس گلی کی دائیں بائیں کی کوٹھیوں سے نئی چمکتی گاڑیاں آتی جاتی دکھائی دیں گی جن میں صاف شفاف گلابی سیبوں جیسے چہروں والی صحت مند جوان عورتیں اور بچے کھلی کھلی مسکراہٹیں لیے پْرسکون بیٹھے باتیں کر رہے ہوں گے۔ ان گاڑیوں اور کوٹھیوں والوں پر ایک چیز کا خمار سب سے زیادہ محسوس ہوگا- جی ہاں، بے فکری کا خمار۔ یہی وہ نعمت ہے جس سے ہم جیسے نچلے طبقے کے لوگ محروم ہیں اور عمر بھر محروم رہتے ہیں۔زندگی برسوں کی تپسیا کے بعد خوشحالی کے دو جام پلا بھی دے تو بھی صرف پیاس ہی بجھ پاتی ہے، خماری نہیں آتی۔ خماری تو آتی ہے ہلکے اور سوچوں سے تہی ذہنوں میں۔ بھاری اور بوجھل دماغوں میں صرف غم اور تکلیفیں ہی جگہ بناتی ہیں۔ خیر مجھے قسمت کا رونا نہیں رونا۔ بات قسمت کی ہے بھی نہیں۔ ہاں اگر انصاف سے- پر مجھے ایسی سوچ کو بھی دماغ میں جگہ دینے کا قطعی اشتیاق نہیں۔ دماغ تو پہلے ہی الجھنوں کی سرائے ہے پھر یہ بے فائدہ سوچیں- ہاں سوچنے کی بات اگر ہے تو اس وقت صرف یہ کہ آج دفتر سے تاخیر کا بہانہ کیا تراشنا ہے۔ میری روز روز کی تاخیر پر بیگم نواز کسی دن فیکٹری سے حساب ہی نہ چکتا کردیں۔ ویسے میں بیگم نواز کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتی۔ مسٹر معین احمد، جو میرے لائن مینیجر ہیں ایک ہی سادہ سا جملہ ہمیشہ بولتے ہیں‘‘ مس نورین! آج پھر ۱۰ منٹ کی تاخیر؟کل ایسا نہ ہو’’ اور میں زیرِلب سنجیدہ سی مسکراہٹ کے ساتھ ‘‘جی سر’’ کہہ کر سیدھی اپنی کرسی پر براجمان۔ مسٹر توقیر، فیکٹری کے سی ای او، صرف اپنے شیشے کی دیواروں والے آفس سے ایک گہری نظر سے دیکھیں گے اور پھر اپنے کام میں مشغول۔ مگر یہ چیف کوآرڈینیٹر بیگم نواز! ان کے نام اور اونچی ایڑھی کی جوتی کی ٹپ ٹپ سے تمام سٹاف خواتین دہل جاتی ہیں۔ وہ اپنے تئیں فوجی جرنیل ہیں۔ ۲۴ سالہ لحیم و شحیم بارعب جثہ اور اس پر مردانہ بشاشت کی ملمع کاری۔ بہت دم خم والی خاتون ہیں۔اْن کی فطری چستی اور رعب داب کے طفیل فیکٹری میں انھیں اْن کے عہدے سے زیادہ بڑا اختیار تفویض کیا گیا ہے۔ بالخصوص فیکٹری میں ملازم لڑکیوں پر انھیں پورے کا پورا اختیار ہے۔ وہ کسی کو کسی بھی پیشہ ورانہ یا ذاتی غلطی پر ڈانٹ بھی سکتی اور فیکٹری سے چلتا بھی کر سکتی ہیں۔ ابھی کچھ ہفتوں پہلے کا واقعہ ہے۔اسمافیکٹری کے ہیڈ کلرک کی موٹرسائیکل پر تاخیر کے خوف سے لفٹ لے کر فیکٹری کے گیٹ پر اتری تو گیٹ کیپر نے ‘‘اچھا تو یہ قصہ ہے!’’ کے سے انداز میں اپنی آنکھوں کو حرکت دی۔ اگلے ہی روز اسماء کو اظہارِوجود کا نوٹس تھما کر اپنی سیٹ پر بیٹھنے سے روک دیا گیا۔ اسی دن شام کو نوٹس کے جواب کا انتظار کیے بنا اسے برطرف کردیا گیا۔ مختصر سی وجہ بتائی گئی کہ اگر فیکٹری کے ملازمین اور ملازمات کے مابین اس طرح کے روابط بڑھنے لگ جائیں گے تو ادارے کی نیک نامی پر حرف آئے گا۔جو دوسری لڑکیاں کام کرتی ہیں ان پر بھی بْرے اثرات ہوں گے۔ یوں اسماء ۴ سال فیکٹری میں کام کرتی کرتی اپنی غلطی یا بے احتیاطی کی نذر ہوگئی۔ میں بھلا کس کھیت کی مولی ہوں؟ جمعہ جمعہ آٹھ دن ہوئے ہیں ملازم ہوئے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں ایم بی اے ہوں، ذہین ہوں اور اپنے کام میں خاصی مہارت بھی رکھتی ہوں۔ہوں تو میں ایک جونیئر اکاؤنٹس آفیسر ناں! نوکر کیا نخرہ کیا! لیکن میرا دماغ، اسے میں کیسے سکون میں رکھوں؟ ہر وقت عجیب سوچیں اور عجیب عجیب تجویزیں دیتا رہتا ہے۔ صبح جب میں دفتر کے لیے نکلتی ہوں تو بہار کی خوشگوار ہواؤں کے ذریعے پیغام ملتا ہے کہ میں بس سٹاپ پر آفس وین کے انتظار کو ترک کرکے فضول میں پیدل چلتی جاؤں۔ بے سمت، بے منزل۔ بس چلتی جاؤں اور انتظار کی کوفت نہ سہوں۔ ایک دو بار اس تجویز پر عمل پیرا بھی ہوئی ہوں مگر نتیجہ وہی پہلے والا، احساسِ کمتری کے شعور کی ٹیسیں۔ ایسا کیوں نہ ہو؟ ہمارا محلہ اندرونِ شہر میں ہونے کے باجود کسی پس ماندہ قصبے کا نقشہ پیش کرتا ہے۔ ٹوٹی پھوٹی کھڈوں والی سڑکیں، پاس بدبودار نالے سے ۴۲ گھنٹے اٹھتی سرانڈ، ہمہ وقت گاڑیوں کا غْل، گرد سے اَٹی فضا اور سہمے سہمے لوگ-85 تیسری دنیا کی تیسری درجے کی بودوباش میں پیدا ہونا ایک حادثہ ہے مگر اس فضا میں پلنا، بڑھنا اور زندگی بسر کرنا کسی سانحے سے کم نہیں ہوتا۔ خاص طور پر جب آپ پڑھ لکھ جائیں اور اپنے ہی وجود کو اپنے ماحول میں پرایا محسوس کرنے لگیں۔محسوسات کا عمل بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے اور جب دل آپ کے قابو میں نہ ہو تو یہ تکلیف دوگنا ہوجاتی ہے۔ میری تکلیف بھی ان دنوں دوگنا ہے۔ ۲۷ برس کی ہوچکی ہوں۔ امی شادی کے لیے پریشان ہیں اور میں اپنے مستقبل کے لیے۔ گویا مجھے اپنا مستقبل اپنی شادی میں نظر ہی نہیں آتا۔ مجھے تو کچھ اور چاہیے، ایسی چیز، ایسی متاع یا ایسی ذات جو مجھے وہ شے عطا کرے جس سے مجھے ابدی بے فکری نصیب ہوجائے۔ پھر میں بھی چاہے آفس وین پر آؤں یا لوکل بس پر- اْس بچی کی طرح مسکرا سکوں گی جو اپنی ماں کے پہلو میں کالے رنگ کی اْس بڑی کار میں بیٹھی تھی جو سرخ بتی پر ہماری آفس وین کے بالکل ساتھ کھڑی تھی۔ کتنی سچی اور خالص مسکراہٹ تھی اس کے چہرے پر۔ ایسی مسکراہٹ جس سے سنجیدگی خوف کھائے۔ کاش وہ مسکان سب کو مل جائے کاش سارا شہر ہی وہ مسکان اوڑھ لے۔پھر وہی خیالات کی قطاریں، وہی یوٹوپیا! آج پھر میں نامعقول ذہن کی چکنی چپڑی باتوں میں آگئی تھی اور آفس وین چھوٹ گئی۔ اب پورے ۱۵ منٹ لیٹ ہوں، خدا خیر کرے! میں سہمی سہمی فیکٹری کے گیٹ پر پہنچی تو گیٹ کیپر کے ماتھے پر شکنیں ڈالے بِنا، دروازہ کھولنے پر عجیب سی خوف آلود حیرت ہوئی۔ اْس نے میری تاخیر کی ذرا پروا نہ کرتے ہوئے اپنا موبائل فون کانوں پر لگائے رکھا اور کسی گہری فکرمندی سے اپنے کسی عزیز کا احوال دریافت کرتا رہا۔ میں بھی اْسے نظر انداز کرکے اپنے سامنے شیشے کا دروازہ آہستگی سے کھول کر اندر داخل ہوگئی۔ حیرت کا دوسرا جھٹکا۔استقبالیے پر سے تمام سٹاف غائب تھا حتیٰ کہ لفٹ آپریٹر اور خاکروب بھی جو اس ہال میں ہمہ وقت موجود رہتے ہیں، اس وقت موجود نہ تھے۔ اب میں مکمل گھبراہٹ اور خوف کی گرفت میں آگئی تھی۔ اس سراسیمگی میں، میں لفٹ کی طرف بڑھتے بڑھتے ایک دم رکی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ پہلے بھی جب کبھی میں جسمانی مشق کرنے کے موڈ میں ہوتی تھی تو لفٹ کے بجائے سیڑھیوں کے ذریعے اپنے کمرے میں پہنچتی مگر آج جسمانی ورزش یا اس قسم کی دوسری بیہودہ وجہ نہ تھی بلکہ بے وجہ اور بے چاہے سب ہو رہا تھا۔پہلی منزل پر پہنچ کر بادلِ ناخواستہ میری آنکھیں کانفرنس ہال کے دمکتے شیشے کے دروازے پر پڑیں۔ تمام آفس سٹاف اور عہدیداران ہال میں جمع تھے اور انتہائی انہماک سے جنوبی دیوار پر آویزاں سکرین پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ یقینا فیکٹری کے مالکان اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کے احکام پر کوئی ہنگامی اجلاس بلایا گیا ہوگا یا کسی خاص نوعیت کی پریزینٹیشن دی جا رہی ہوگی۔ میں نے دونوں آنکھیں پوری طاقت سے کھولتے ہوئے امکانی صورت سوچی اور ساتھ ہی دھیرے سے ہال کا دروازہ اندر کی جانب کھول دیا۔ دروازے کے قریب کی کرسیوں پر بیٹھے چند سٹاف ممبران کی آنکھیں دفعتاً مجھ پر اٹھیں مگر ساتھ ہی سب مڑ کر ٹی وی سکرین کی طرف متوجہ ہوگئے۔ سکرین پر کوئی دفتری پریزینٹیشن نہیں بلکہ ایک نجی ٹی وی چینل پر نیوز بلیٹن دیا جا رہا تھا۔ ‘‘اندرون لاہور بم دھماکا!’’خوف کی ایک شدید لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں بجلی بن کر کوند گئی۔ میں نظریں سکرین پر گاڑے وہیں پتھر بنی کھڑی رہی۔ نیوز نمائندہ بول رہا تھا ‘‘شہر کے اس نیم تجارتی گنجان آباد حصے میں صبح ۸ بج کر ۴۰ منٹ پر ایک ہولناک بم دھماکا ہوا ہے۔ دھماکے سے گورنمنٹ جناح سکول اور اس سے ملحقہ عمارتوں کے ساتھ ساتھ رہائشی کوارٹرز بھی ملیا میٹ ہوگئے ہیں۔ بڑے پیمانے پر جانی نقصان کا خدشہ ہے۔’’ گورنمنٹ جناح سکول سے ملحقہ رہائشی کوارٹر!!! میرے خدایا!!! اوہ دیکھیے مس نورین کو کیا ہوا؟ اْٹھیے، پکڑئیے انھیں، دھیان سے بھئی دھیان سے۔ میڈم کو بلا ئیے۔بے ہنگم شور، چیخیں، سسکیاں اور ماتم کی دل فگار آوازیں- ٹھپ ٹھپ، ادھر دیکھیں، اس کنکریٹ سِل کے نیچے بچے کی ٹانگ پھنسی ہے، اٹھائیے، جلدی کیجیے، اٹھائیے۔ ایک طرف ہو جائیے۔ مہربانی آپ لوگ یہاں رش نہ ڈالیے۔ سکول کے ملبے تلے ابھی بہت سے بچوں کی نعشیں دبی پڑی ہیں۔ کوارٹروں کی باری بعد میں آئے گی۔ ہم آپ ہی کے پیاروں کی تلاش میں مصروف ہیں۔ اسٹریچر لائیے۔ جلدی، اور آگے یہاں ٹھیک ہے۔اس بچی کی حالت بہتر ہے۔ اسے سامنے میڈیکل کیمپ میں پہنچائیے۔ آہ ! آہ! وہ دیکھیے اْدھر، کوارٹر کے تباہ شدہ غسل خانے کی نالی سے خون رِس رہا ہے۔ ہٹیے۔ رضاکار بھائی! یہ فوٹو ہے۔ کوئی ملا ایسا بچہ۔ زندہ یا ٹھہرئیے جانے کتنے گھنٹوں بعد مجھے کچھ ہوش آیا۔ میں ایک میلی سی کھاٹ پر لیٹی تھی اور میری بائیں ٹانگ اکڑی ہوئی تھی۔ دائیں بائیں کچھ جانے انجانے پریشان حال چہروں کا ہجوم تھا۔ کھاٹ پر بیٹھی میری ۲ رشتے دار خواتین مجھے دستی پنکھے سے ہوا دے رہی تھیں۔ کچھ اور گھڑیاں گزر گئیں۔ اب میں مکمل اپنے حواس میں تھی اور اٹھ کر کھاٹ پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھ گئی تھی۔میں نے بھاری پپوٹے اٹھائے۔ یہ ہمارے تباہ شدہ کوارٹر کا آنگن تھا۔ آنگن کیا ملبے کا ڈھیر تھا۔ تاحدِنظر زمین بوس دیواریں اور چھتیں بین کر رہی تھیں۔ ریسکیو کے جوان، رضاکار، پولیس اور محلے کے کچھ آشنا بزرگ اور نوجوان لڑکے اینٹیں، پتھر اور تڑے مْڑے دروازے اِدھر اْدھر کھسکا رہے تھے۔ ماحول پْر شور تھا۔ دورونزدیک سے ایمبولینس کی چنگھاڑیں فضا کو برابر سوگوار کیے ہوئے تھیں۔ بائیں جانب دس پندرہ گز کے فاصلے پر محلے کے مردوں کا ہجوم تھا۔ کچھ خواتین ننگے سر ملبے کے ڈھیر پر اکڑوں بیٹھی تھیں۔ باقی بے یقینی کے عالم میں تلاشتی آنکھوں کے ساتھ کھڑی ادھر ادھر گھورتی جاتی تھیں۔ چند عورتیں اپنے گھٹنوں کا سہارا دیے محلے کی ایک بڑی بوڑھی حسن بی بی کو کھڑولی پر بٹھائے اس کے آنسو پونچھ رہی تھیں۔ہمارے آنگن کی ایک نکڑ میں چند فٹ چوڑی پھلواڑی کی جگہ ٹیڑھے میڑھے ٹین کے تختے گرے پڑے تھے۔ پھولوں بھرے پودے اْن کے نیچے دب کر مر گئے ہوں گے! نیم کا جواں عمر پیڑ البتہ زخم زخم شاخیں اٹھائے صدمے کی حالت میں ساکت کھڑا تھا۔ چاروں طرف ایک تناؤ سا تھا۔ ایک غیر مرئی خوف کا سایہ جو ان تباہ شدہ بام و در میں گردش کررہا تھا۔ لوگ ہاتھ باندھے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ شہر کراچی کی طرح اب لاہور کی گلیاں بھی جل رہی ہیں۔ ہمارے ملک پر تو کم بختی چھائی ہوئی ہے۔ ہمارے اپنے اعمال ہی تو اچھے نہیں ہیں۔ اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔یہ جہادی تنظیمیں اور دہشت گردوں کے ناموں کا تو بس بہانہ ہے۔ اصل میں توہماری اپنی بداعمالیاں اور بددیانتیاں ہی ہمیں ہلاک کر رہی ہیں۔ یہ بلیک واٹر کیا ہے کسی نے بیچ میں استفسار کیا۔ کہتے ہیں کوئی امریکی غنڈوں کا گروہ ہے جو ہمارے ملک کے سکون کو غارت کرنے کی سازشیں کر رہا ہے۔ پتا نہیں کون ہمیں توڑ رہا ہے۔ غیر یا اپنے۔ بس سوہنے رب سے ہی دست بستہ دعا ہے کہ ہم پر رحم کرے، معاف کردے ہمیں۔میرا دماغ بھاری ہو رہا تھا، میں نے اپنی جلتی ہوئی آنکھوں کو بمشکل کھولا اور بغیر سوچے اٹھ کھڑی ہوئی۔ برہنہ پا دو تین ڈگ ہی بھرے ہوں گے کہ پاس بیٹھی کسی خاتون نے کھڑے ہو کر میرا بازو تھام لیا ‘‘بیٹا کہاں جا رہی ہو؟’’آواز جانی پہچانی تھی مگر اس میں اپنائیت نئی نئی تھی۔ بیگم نواز کی آواز نے اب مجھے پوری طرح بیدار کر ڈالا تھا۔ ‘‘میڈم! میرا گھر! میری امی وہاں ہوں گی۔’’ اس لمحے پاس بیٹھی رشتے دار خواتین کی وحشت ناک چیخیں فوارے کی طرح ہوا میں بلند ہوئیں۔ میں سہم کر تھرا سی گئی۔ بیگم نواز نے لپک کر مجھے اپنے سینے میں سمو لیا۔تم بہت بہادر بیٹی ہو۔ تمھیں خدا پر بھروسا رکھنا ہے نورین۔ وہی سب خلاؤں کو پْر کرنے والا ہے۔ اس کی مرضی کے سامنے ہماری کچھ اوقات نہیں۔ اْس کی رضا ہی ہماری رضا ہے۔ وہ سب سے پیارا ہے۔ امی ابو بھی اْسی پیارے کے پاس چلے گئے ہیں۔ آخری جملہ بولتے ہوئے بیگم نواز نے ایک گہری ہچکی لی اور ساتھ ہی مجھے اپنے ساتھ یوں کس کر چمٹا لیا جیسے انھیں بھی خود کو ہلکا کرنے کے لیے کسی سہارے کی حاجت تھی۔میں پہاڑوں روئی اور اتنی کہ میرا رونا سن کے ملبے کے خون آلود پتھر ، اینٹیں اور سریے بھی رو پڑے۔ پوری فضا پْر درد کراہوں کے بیچ سینہ کوبی کرنے لگی تھی۔ میں چیخ چیخ کر بول رہی تھی۔ ‘‘اے ظالم انسان! کہاں ہے تو؟ کیا چاہتا ہے؟ اس بربادی سے تیرا کیا مفاد وابستہ ہے؟ یہ بربادی، یہ انسان کشی، کیا انسان ترقی کر رہا ہے؟ انسان ہی انسان پر ایسے کیسے ظلم کے پہاڑ ڈھا سکتا ہے جو وحشی درندوں کو بھی پانی پانی کرتے ہیں۔ کیا امن اور ترقی کا حصول بموں سے ممکن ہے؟ یہ لوگ واپس نہیں آئیں گے، میری ماں واپس نہیں آئے گی، میرا باپ کبھی نہیں لوٹے گا اور ہم جو زندہ بچ گئے ہیں کیسے زندہ رہیں گے؟دہشت آسیب کی طرح میری روح میں جمنے لگی تھی۔ خوف میری کھال سے ہوتا ہوا ہڈیوں میں سرائیت کر رہا تھا۔ ایسے میں میں بڑبڑائی تھی۔ میڈم نواز!مجھے زندہ نہیں رہنا۔ مجھے بھی اسی
ملبے کے نیچے کہیں دفنا دیجیے جہاں میرے ماں باپ کی لاشیں پڑی ہوں گی۔ اس یادداشت کے ساتھ کیسے جی پاؤں گی جس میں میرے پیارے موجود ہی نہ ہوں گے۔ اے میرے خدا! میں نے تجھ سے بے فکری کی زندگی مانگی تھی تو نے تو مجھے ہر فکر سے ہی آزاد کردیا۔ میڈم نواز مجھے اپنے ساتھ چمٹائے ہولے ہولے ملبے سے یوں دور لیے جا رہی تھیں جیسے کوئی ماں اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت دولھے کی کار کے طرف لیے جاتی ہے۔