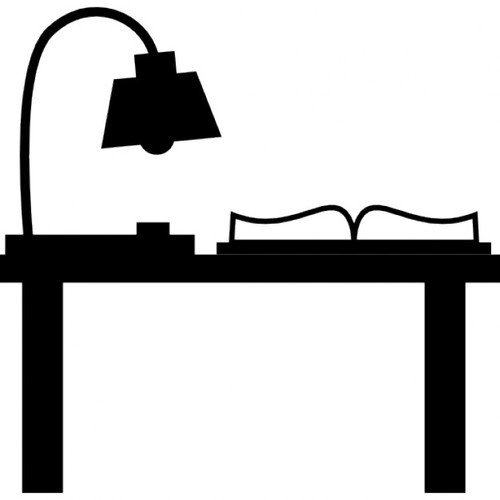کل مختصر دورانیے کے لیے آبائی شہر چنیوٹ جانا ہؤا۔ دارالدعوۃ السلفیۃ اور مکتبہ سلفیہ کے روحِ رواں، مولانا عطاء اللہ حنیف بھوجیانی رحمہ اللہ کے پوتے اور یارِ دیرینہ حماد شاکر نے ایک دن قبل بتایا کہ اتوار کو وہ لکڑی کی کچھ مصنوعات کی خریداری کے لیے سلانوالی شہر جائیں گے۔ اس بہانے مجھے بھی دعوتِ ہمسفری دے دی۔ حماد صاحب کی دلربا شخصیت تو ایک الگ تحریر کی متقاضی ہے۔ مختصراً عرض کروں تو میری زندگی میں جو لوگ ہمیشہ ٹھنڈی ہوا بن کر راحت، حوصلے، عزت افزائی اور آسانی کا باعث رہے ہیں، ان میں یہ شخص صفِ اول میں ہے یا سرِ فہرست۔ ہم زندگی میں بہت سے طباعتی منصوبوں میں شریک رہے۔ حماد صاحب عربی گرامر میں میرے استاد بھی رہے لیکن دوستوں سے کچھ سیکھنا مشکل تر ہوتا ہے سو یہی بات پایۂ ثبوت کو پہنچی۔ ایمان کی تفسیر دیکھنی ہو یا یقین کی مجسم صورت، ادب اور احتیاط کے قرینے سیکھنے ہوں یا خاموش خدمت کا قدِ آدم نقش یہ شخص لمحے کے ہزارویں حصے میں صفحۂ ذہن پر ابھر کر خیال پر قابض ہو جاتا ہے۔
پرسوں رات میں نے فون پر ساتھ چلنے کی ہامی بھری۔ لکڑی کے کام کے حوالے سے ایک ایسے شہر جانے کا پروگرام بن چکا تھا جس سے میں لاعلم تھا۔ کسی زمانے میں کمپیوٹر گرافکس کی تربیت دینے کے لیے ایک کالج بنایا تھا۔ نمود سے لاپروا دوستوں نے مجھے پرنسپل بنا دیا۔ یہ کالج لاہور کے گرافک ڈیزائنروں اور کمرشل آرٹسٹوں میں نوے کی دہائی کے نصفِ آخر تک مقبول رہا اور بعد میں بھی قریب دس برس تک جزوی طور پر فعال رہا۔ یہیں کے ایک فارغ التحصیل ڈیزائنر ذاکر صاحب نے بھی حماد صاحب کی ہمسفری کے لیے درخواست کی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ سرگودھا سے تیس کلومیٹر دور سلانوالی شہر، جس کا اب تک محض نام سن رکھا ہے، لکڑی کے فرنیچر اور آرائشی مصنوعات کے حوالے سے اپنی جدا پہچان رکھتا ہے۔ خیر عصبیت بھی انسان کے اندر دب کر کہیں بیٹھی ہوتی ہے۔ سو یہ شیرنی بھی جاگ اٹھی اور میں نے کہا کہ ہم چنیوٹ بھی چلیں گے اور میں آپ کو وہاں کا کام دکھاؤں گا۔ سوچا اس بہانے حماد بھائی کو عمر حیات کی حویلی بھی دکھا دوں گا اور مغل عہد میں تعمیر ہونے والی نواب سعد اللہ خان کی یادگارِ زمانہ شاہی مسجد کے گنبدوں کی اندرونی نقاشی کی زیارت بھی ہو جائے گی۔ مسجد کی تعمیر میں سنگِ لرزاں اور سنگِ سیہ استعمال ہؤا ہے۔ سنگِ لرزاں کی روایت مجھ تک سینہ بہ سینہ پہنچی ہے لیکن کسی مینار کو لرزا دینے کی سعادت کبھی حاصل نہیں ہوئی اور نہ کوئی ایسا سعادت مند ملا۔ یاد رہا تو واپسی پر مولوی کی برفی یا کھنڈوئے (ایک ذات) کا پتیسہ بھی خرید لیں گے جسے میری منکوحہ مالکن مشکل ہی سے کھانے دیں گی۔
طے تو یہ ہؤا تھا کہ پہلے سلانوالی جائیں گے اور واپسی پر چنیوٹ۔ مگر خدا کو یہ ترتیب منظور نہ تھی۔ جن صاحب سے سلانوالی میں ملنا تھا، وہ سہ پہر سے پہلے دستیاب نہیں تھے سو قریب بارہ بجے چنیوٹی فرنیچر کے بازار پہنچے۔
شہر اب لکڑی کے سامان کی بڑی منڈی میں تبدیل ہو چکا ہے۔ ہر گلی اور بازار میں لکڑی کا سامان مل جاتا ہے البتہ کچھ علاقے مخصوص بھی ہیں۔ قدیم آرکی ٹیکچر کے درمیان جدید مغربی طرز پر بنے بنک، الیکٹرانکس سامان کے شو رومز اور فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹس مخمل پر ٹاٹ کے پیوند دکھائی دیتے ہیں۔ جیسے کوئی کلیوں والے سفید کرتے پر سرخ ٹائی باندھ لے یا چوڑی دار پاجامے کے ساتھ جوگرز پہن کر محوِ خرام ہو۔ آپ چاہیں تو خرام سے ایک نقطہ اڑا لیں۔
تہذیبِ نو کے منہ پہ وہ تھپڑ رسید کر
جو اس حرامزادی کا حلیہ بگاڑ دے
اقبال
دکانوں پر دو درجوں کا کام دکھائی دے رہا تھا۔ ایک درمیانے درجے کا اور دوسرا نسبتاً غیر معیاری۔ میرے ہم سفروں کو تو گویا ہر چیز اچھی لگ رہی تھی لیکن معیار کے فرق کو وہ بھی سمجھ رہے تھے۔ قیمتیں بھی اسی اعتبار سے لگائی گئی تھیں۔ مجھے البتہ کچھ شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ جس معیار کا کام میں ان دوستوں کو دکھانا چاہتا تھا، وہ نظر نہیں آ رہا۔ دکانوں پر مشینی کھدائی سے بنے بیل بوٹوں والا فرنیچر بھی موجود تھا جس کو باہر سے آنے والے بظاہر دولت مند لیکن کم ذوق ہاتھ کے کام سے ممتاز نہیں کر پا رہے تھے۔ میں ذہن پر زور دے رہا تھا کہ ان خاندانوں کے نام یاد آ جائیں جن کو تاریخ نے اس فن میں امامت کا درجہ دیا تھا۔
عمر دو برس تھی جب میرے والدمیاں خالد محمود ہمیں لے کر مستقلاً لاہور منتقل ہو گئے۔ برسوں بعد کوئی شادی یا فوتگی ہوتی تو ہم رات بھر کے لیے چنیوٹ چلے جاتے۔ میرے لڑکپن تک یہ سلسلہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ اب کبھی کبھی والدہ کے ساتھ ننھیالی گھر سے ان کے جہیز کی کچھ چیزیں نکال کر لاہور منتقل کرنے کے لیے جاتا تو پرانے ملازمین میں سے کچھ عمر رسیدہ لوگ مدد کو آ جاتے۔ وہ محبت اور عقیدت بھی دیدنی تھی۔ انسان کیسے رشتوں میں بندھے ہوئے تھے جن کا تصور اب افسانہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ لوگ ایسے جسم کی طرح تھے جس کے اعضاء بکھیر دیے گئے ہوں اور وہ سرکتے سرکتے بار بار یکجا ہو جاتے ہوں۔ کمان جیسے قد، گہرے رنگ کے حاشیے والی تھکی ہوئی آنکھوں اور ناہموار ٹیکسچر والی کھال کے ساتھ جب یہ ایک دوسرے کے سامنے آتے تو ایک لمحے میں کمان کی چھڑی بن جاتی، حاشیہ معدوم ہو کر اپنے مرکز میں سورج روشن کر لیتا اور کھال پر کندہ خطوط غائب ہو کر جھیل کی ہموار پُر سکون سطح بن جاتے۔
چنیوٹ کے بارے میں مجھے صرف وہ معلومات دستیاب تھیں جو بڑوں کی گفتگو سے کشید کی تھیں۔ والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ چنیوٹ میں مُحرم کے دوران عاشور کے جلوس میں بیسیوں عقیدت مندوں کے شانوں پر منوں وزنی لکڑی کا تعزیہ چلتا جو فنکاروں کی مہارت کی معراج سمجھا جاتا تھا۔ اس کی تیاری میں برسوں کی محنت لگتی۔ یہ تعزیہ عرق ریزی، تخلیقی وفور، عقیدت بلکہ جسمانی اور روحانی توانائیوں کا حاصل ہوتا تھا۔ شہر کے ترکھانوں اور مُنبَّت کاروں کے مختلف خانوادے اپنی اپنی فنی روایت کی نمائندگی ان تعزیوں کے ذریعے کرتے۔ ان تعزیوں میں سے بعض کی اونچائی پچاس فٹ سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ یہ آٹھ منزلہ مُنقش عمارت نما ہوتے جن کو جنت میں حضرت امام حُسین رضی اللہ عنہ کو عطا ہونے والے محل سے تعبیر کیا جاتا۔ پنجتن کے نام سے مقدس ارکانِ خمسہ کی شخصیات کو مختلف گنبدوں اور میناروں کی صورت علامتوں سے ظاہر کیا جاتا۔ تعزیوں کے فنی مقام کا تعین کرنے کے لیے شہر کے بزرگ اہلِ علم و فن پر مشتمل ایک ایوان تشکیل دیا گیا تھا جو پہلے، دوسرے اور تیسرے درجے کا اعلان کرتے۔ یہ افراد علم و فضل ،وسیع المشربی اور فن سے محبت کی بنیاد پر چنے جاتے۔ ان میں ہر مسلک اور نقطۂ نظر سے متعلق لوگ ہوتے تھے۔ میرے دادا شیخ عبد الرحیم علیگ بھی اس مجلس کا حصہ تھے حالانکہ وہ مسلکاً دیوبندی اور اہلِ حدیث فکر سے قریب تر تھے۔ سرسید احمد خان صاحب کی تربیت اور محمد علی جوہر کی سرپرستی سے ان کے ہاں ملی تشخص کا تحفظ اور روایتی فنون کا فروغ بہت اہمیت رکھتا تھا۔
میرے تایا جان شیخ مسعود احمد مگوں قریب چورانوے برس کی عمر میں کچھ سال پہلے ہم سے جُدا ہوئے۔ میری خواہش پر ان کے قلم سے کچھ لوگوں کے خاکے تخلیق ہوئے جن میں جگر مراد آبادی، اشفاق احمد، نور جہاں، چراغ حسن حسرت، خالد محمود (میرے والدِ گرامی)، شاہد عمر (میرے پھوپھی زاد بھائی) اور احقر سجاد خالد شامل ہیں۔ میرا خاکہ البتہ میری خواہش پر نہیں لکھا گیا تھا کہ ان بزرگوں کا مزاج شاہانہ تھا۔ ان خاکوں کے علاوہ ایک دلچسپ مضمون چنیوٹ کی داڑھیاں بھی سامنے آیا جو خاصے کی چیز ہے۔ اسی طرح وہ چنیوٹ کے مُنَبت کاروں کے فن اور تعزیہ کی روایت پر بھی ایک مضمون تحریر کرنا چاہتے تھے جس کے مندرجات کا ذکر اپنی گفتگو میں کرتے تھے۔ یہ مضمون نہیں لکھا جا سکا۔ خود میری توجہ ان دنوں اقبال، خلیل جبران، سید مودودی، حسرت موہانی، ابولکلام، مولانا اصلاحی، حمید الدین فراہی اور فیض کی طرف مرکوز تھی سو ان فنکار گھرانوں کے نام لوحِ ذہن پر نقش نہ ہوسکے۔ میں کبھی خواجہ بدر السلام فروغی مرحوم کی مجلس میں ہوتا، کبھی سراج منیر بھائی کے گھر شام کو رات کرتا، کبھی جاوید احمد غامدی صاحب سے ملاقاتیں کرتا اور کبھی مولانا اسحاق بھٹی مرحوم کی موجودگی کی خبر پا کر اُن کے حلقے میں اُڑ کر پہنچتا۔ ان مصروفیات کے ساتھ ساتھ وقت کا بیشتر حصہ خوشنویسی کے اساتذہ کی خدمت میں صرف ہوتا۔ جو وقت بچ رہتا وہ مختلف مذہبی اور ثقافتی تنظیموں یا تلاشِ رزق کی سرگرمیوں میں کھپ جاتا۔
ذہن پر بہت زور دیا لیکن ایک خاندان کے نام کے سوا کچھ یاد نہ آیا۔ یہ سطور لکھتے ہوئے بھی کچھ نام سطح پر آنے سے پہلے ڈوب ڈوب جاتے ہیں۔ مجھے یاد آیا کہ ایک خاندان پِرجھا کے نام سے تھا جو منبت کاری میں یکتا تھا۔ دکانوں کے نام ایک تو خطاطی سے اپنے عشق کی بنیاد پر دیکھ رہا تھا اگرچہ نظر ہر بار نامراد لوٹتی رہی اور دوسری غرض یہ تھی کہ کسی فنکار گھرانے کا نام سامنے آ جائے تو دوستوں کو وہاں لے جاؤں۔ ایسے میں ایک دکان پر پِرجھا یا پرجہ کا لفظ دکھائی دیا اور ہم اس میں داخل ہو گئے۔ وہاں مُنبت کار صابر صاحب سے ملاقات ہوئی جن کی رہنمائی سے ہم سب نے ِاس فن کی تحسین کے کچھ زاویے سیکھے۔ ان کے استاد ندیم پرجھا موجود نہیں تھے۔ یہ وہی خاندان ہے جس کے بزرگوں رحیم بخش پرجھا اور الٰہی بخش پرجھا نے عمر حیات کی حویلی میں نادرِ روزگار کام کر کے اسے چنیوٹ کے ماتھے کا جُھومر بنا دیا تھا۔ اس کام کو دیکھ کر احباب مطمئن دکھائی دیے کہ اب تک اس سے بہتر کام ان کی نظر سے نہیں گزرا۔ایک مصور کا کام دیکھ کر ہمارے ایک فن شناس بزرگ غلام رسول منظر رقم نے مجھ سے کہا تھا۔سجاد میاں! اُس دن میں اندھا ہو گیا تھا کہ اب کوئی فنپارہ سامنے آیا تو وہ معیار نہ پا کر کیسے دیکھ پاؤں گا۔ یہ ایرانی مصور محمود فرشیان کا کام تھا جو شاید پچاس ساٹھ برس پہلے لاہور میں لارنس روڈ پر موجود ایک گیلری میں اپنے کام کی نمائش منعقد کر کے گئے تھے۔ یہ نمائش دیکھنے میرے ساتھ عبدالرحمٰن چغتائی کے برادر عبداللہ چغتائی اور اُستاد یوسف سدیدی تھے۔
منظر رقم حافظ محمد یُوسُف سدیدی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے اور نوائے وقت کی سُرخیاں لکھتے تھے۔ نوے کی دہائی میں انٹرنیٹ کی سہولت نئی نئی دستیاب ہوئی تو میں نے محمود فرشیان کا کام تلاش کر کے ایک پینٹنگ کا رنگین پرنٹ منظر رقم صاحب کی خدمت میں پیش کیا اور ڈھیروں دعائیں وصول کیں۔
پرجھوں کی دکان سے نکل کر ہم تینوں رکشا لے کر عمر حیات کی حویلی پہنچے۔ میں پچھلے برس کے آخر میں کرونا کا شکار ہؤا تھا۔ اس کے نتیجے میں اب تک بہت سے عوارض ہمراہ ہیں۔ ٹانگ میں کمزوری کی وجہ سے رکشے پر چڑھنا اور اترنا بہت مشکل رہا اور دائیں بازو پر زور ڈالنے سے جو درد اٹھا وہ حویلی پر پہلی نظر پڑنے تک قائم رہا۔
پہلی نظر کی محبت تو جان لیوا ہوتی ہے لیکن ہر بار پہلی نظر سے قلب جاری ہو جائے - یہ واردات کم کم ہوتی ہے۔ کون جانتا ہے کہ ہم ایک عمارت کو دیکھ رہے تھے یا بیسیوں اہلِ فن کی تراشی ہوئی بہشت کے دروازے پر کھڑے تھے جس میں اب تک کا تصورِ حسن منجمد ہو چکا ہے۔ منجمد کہنے سے مراد جامد نہیں بلکہ یکجا ہونا ہے۔ لیکن اس کیفیت کو منجمد کہنے پر مجبور ہوں۔ جامد اس لیے نہیں کہ مصوری اور آرکی ٹیکچر سمیت بصری فنون کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ فن پارے میں حرکت کسے کہتے ہیں۔ وہ سیکھتا ہے کہ ناظر کو کس مقام سے فنپارے میں داخل کرنا ہے اور کس کس جگہ کی سیر کرواتے ہوئے دھیرے دھیرے کنارے تک لے جانا ہے۔ یاد رہے کہ دریا کا کنارہ تو موجود ہو سکتا ہے، فنپارے کا نہیں۔ جیسے ہی آپ آخری منزل پر پہنچتے ہیں تو یہ جادوئی بہشت آپ سے پوچھے بغیر اگلے لمحے پھر سے صدر دروازے میں داخل کر لیتی ہے۔ ہر بار بیچ کے مقامات میں کھلنے والے جھروکوں سے فردوسِ بریں کے نئے جلوے خوش نصیب کے منتظر ہوتے ہیں اور اسے باور کروا دیتے ہیں کہ آتے رہو گے تو ۔۔ اس بار ۔ ہر بار۔۔ کچھ نیا ملے گا۔
اجتماعی دانش کے نتیجے میں بننے والے فنپاروں اور انفرادیت کے مرض سے آلودہ ۔۔ ایجاد کے دعووں سے بوجھل کام میں زمین و آسمان سے بڑھ کر فرق ہے۔ جدید ذہن کو شکستگی بھلی لگتی ہے۔ وہ اسے اینٹیک کے لقب سے یاد کرتا ہے۔ میں ہر فنپارے کی خستگی پر دکھ محسوس کرتا ہوں۔ میرے بس میں ہو تو میں یہ سب کچھ بنتے ہوئے دیکھوں۔ میں ان کاریگروں کی خدمت میں رہ کر اوزار سیدھے کیا کروں۔ ان کی سہولت کا ہر سامان ان کے کہنے سے پہلے لے کر کھڑا رہوں۔ میرے اختیار میں ہو تو میں دیمک کی خدمت میں احساسِ کمتری، اکلاپے، انفرادیت اور روایت بیزاری کے نتیجے میں بننے والے نام نہاد نئے اور تازہ فنپارے پیش کروں جبکہ ممکن ہے یہ کیڑے ایسے کم ذوق نہ ہوں۔
راشد نے کہا تھا
اجل، ان سے مل،
کہ یہ سادہ دل
نہ اہل صلوٰۃ اور نہ اہل شراب،
نہ اہل ادب اور نہ اہل حساب،
نہ اہل کتاب
نہ اہل کتاب اور نہ اہل مشین
نہ اہل خلا اور نہ اہل زمین
فقط بے یقین
اجل، ان سے مت کر حجاب
اجل، ان سے مل!
بڑھو، تم بھی آگے بڑھو
اجل سے ملو،
بڑھو، نو تونگر گداؤ
نہ کشکول دریوزہ گردی چھپاؤ
تمہیں زندگی سے کوئی ربط باقی نہیں
اجل سے ہنسو اور اجل کو ہنساؤ!
بڑھو بندگان زمانہ بڑھو بندگان درم
اجل یہ سب انسان منفی ہیں
منفی زیادہ ہیں انسان کم
ہو ان پر نگاہ کرم
زندگی نے کم ہی سہی ۔۔۔ مجھے خدمت اور حضوری کے ان لمحوں کی دولت سے محروم نہیں رکھا۔ اس مٹھاس اور پیاس سے واقف ہو کر میں ہل من مزید نہ کہوں تو کیا کہوں۔ مجھے یہ چیزیں اپنی اصلی حالت میں درکار ہیں جب رنگ پوری آب و تاب کے ساتھ ٹھیک اپنے حاشیوں میں جلوہ افروز تھے۔ جب ہر قوس مکمل تھی، جب کسی پھول کی پتی اس سے ٹوٹ کر جدا نہ ہوئی تھی۔ مجھے فن کی بہار دیکھنی ہے، شکستگی کی خزاں نہیں۔
شکستگی، خزاں بلکہ اینٹیک کے دلدادہ لوگوں کی بیٹھکوں میں میں اکثر کمزور خط کے پرانے نمونے دیکھتا ہوں جنہیں وہ بڑے فخر سے دیواروں پر سجاتے ہیں۔ ان کے نزدیک اصل قدر، فن نہیں، تباہی ہے۔ ایسے بیماروں کی تسلی کے لیے اینٹیک کاغذ، پرانی طرز کے مخطوطوں، ملبوسات، آلاتِ موسیقی اور سامانِ جنگ ڈھالنے اور تلاش کرنے والی زیرِ زمین انڈسٹری وجود میں آ چکی ہے۔ جس کی بدولت کچھ محنت کشوں کو اندھی دولت سے اپنا حصہ مل جاتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے شرابِ کہن کی خالی بوتلیں بھی نہیں دیکھیں۔ یہ ان کی بھونڈی اور بازاری نقل سے گزر اوقات کر رہے ہیں کیونکہ مقصود محض یہ ہے کہ آنے والا جو ان جیسا خالی باطن ہے، مرعوب ہو جائے۔ سو وہ غریب کیوں نہ مرعوب ہو۔
عمارت کے صحن میں داخل ہوئے تو حیرت نے عقیدت کی صورت اختیار کر لی۔ یوں جینے کے لیے تو اس کا باہری رُخ بھی کافی تھا لیکن صحت اور خوشی کے ساتھ جینے کی آرزو تھی سو دروازے پر پڑا قفل دیکھ کر پریشانی ہوئی۔ اس حال میں نظر دوڑائی تو ایک باریش و مستعد ادھیڑ عمر صاحب کو اپنی جانب متوجہ پایا۔ یہ مشتاق صاحب تھے جو محکمہ اوقاف یا میونسپل کمیٹی کی جانب سے زائرین کی رہنمائی پر مامور تھے۔ محکمانہ گرمجوشی سے ملے اور فوراً چابیاں لے کر آ
گئے۔ صدر دروازہ ہماری توقع سے پہلے ہی کھل گیا اور مجھے یاد آیا کہ والدہ کے ساتھ بچپن میں یہاں آیا تھا۔ یہ بھی یاد آیا کہ اس وقت یہ عمارت زیادہ اونچی تھی۔ مشتاق صاحب نے بتایا کہ 1993 میں ایک طوفان سے اس کی اوپر والی دو منزلیں تباہ ہو گئی تھیں۔داخل ہوتے ہی دیوار و در کی خوبصورتی نے گھیر لیا اور میں صحن کے درمیان ایک سیڑھی جتنی بلند و ہموار دو قبروں کو نہ دیکھ سکا۔ یہ قبریں حویلی کے دو مکینوں کی تھیں۔
صحن میں اس کم نصیب کی قبر تھی جس کے لیے یہ گھر تعمیر کروایا گیا تھا۔ یہ نوجوان اپنے ولیمے کے روز صبح غسل خانے میں زندہ گیا اور لاش نکالی گئی تھی۔ یہ عظیم صدمہ ماں سے کہاں سہا جانا تھا سو وہ بھی چند روز میں بیٹے سے جا ملی۔ اس حویلی کا حُسن اس داستانِ الم کے ساتھ مل کر دلوں میں ہمیشہ کے لیے دنیا کی بے ثباتی کی علامت بن کر زندہ ہے۔ کچھ برس گزرے تو پیچھے رہ جانے والوں نے اس عمارت کو آسیب زدہ جان کر خیر باد کہا۔
صحن کے وسط میں ٹھیک وہیں پر قبریں موجود تھیں جہاں کھڑے ہو کر کوئی زائر اس عمارت کا حسن پوری تجلی کے ساتھ آنکھوں کے ذریعے قلب میں بھر سکتا ہے لیکن یہ آسانی اب وہاں آرام کرنے والوں کو میسر ہے۔ میں نے چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کر لیں اور اس ماحول کو حواس سے برتر کسی منزل پر محفوظ کرنے لگا۔ اس کیفیت میں حماد شاکر سے کہا کہ یہاں کھڑے ہو کر تہذیبی اعتماد اور اپنے وجود پر اعتبار آتا ہے۔ ان کی آنکھیں بلکہ پورا وجود تائید کر رہا تھا لیکن ان کی خاموشی اس سے زیادہ گہری کیفیت بیان کر رہی تھی۔
اس کے بعد مشتاق صاحب ہمیں عمارت کے مکینوں کی کہانی سناتے جاتے اور جا بجا استعمال ہونے والے سامانِ تعمیر و زیبائش کی تفصیل دیتے رہے۔ پہلی منزل کے ہر کمرے میں خستہ حال کتابوں سے بھری الماریاں رکھی تھیں اور ایک بڑے کمرے کو باقاعدہ دارالمطالعہ کا درجہ بھی دیا گیا تھا۔ معلوم نہیں کہ کوئی یہاں کتاب پڑھنے آتا ہے یا نہیں لیکن یہ عمارت تو کتابوں کی جائے پیدائش ہے۔ ہر کمرے کے دروازوں اور کھڑکیوں میں شیشے کا کام اور چھت کی اندرونی آرائش کے نقش و نگار الگ ہیں۔ الماریوں کے گرد لکڑی کا کام
نازک اندام فرشتوں کی کاریگری لگتا ہے۔ جن کو خطاء کی خبر ہی نہ ہو۔ جو اِذنِ کُن پر لبیک کہہ کر عبادت کرتے گئے ہوں۔
میرے لیے سیڑھی چڑھنا انتہائی مشکل تھا اور حماد صاحب منع کرتے رہے کہ آپ اوپر نہ آئیں لیکن میں نے ہر منزل کے کونے کونے تک اور ہر راہداری میں ان کا تعاقب کیا۔ وہ تین نسلوں سے تصویر کے قائل نہیں تھے اور سب جانتے ہیں کہ ان کی شادی کی ایک تصویر بھی نہیں ہے لیکن بیقرار ہو کر کہا۔۔۔۔ یہاں میری تصویر لے لیں۔ جو رہی سو بے خبری رہی