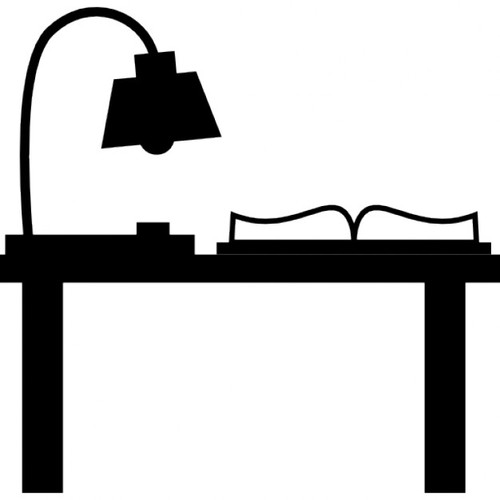ادب
سوکھی ٹہنی
محمد قاسم
ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت پر مبنی ایسا افسانہ جو سچہی کہانیوں سے ہمارے کچے مکان کے ساتھ ہی ان کا دو منزلہ چوبارہ تھا۔ عمر، قد، رنگت، بول چال اور عادات میں ہم جڑواں لگتے۔ ہم دونوں کا ساتھ چاند اور ستارے کی طرح تھا، جہاں میں وہاں وہ اور جہاں وہ وہاں میرا ساتھ بھی پکا۔ ہم ہر جگہ ساتھ ساتھ ہی نظر آتے۔ گلی میں، مسجد میں، اسکول میں، کھیل کے میدان میں، دْکان میں ہر جگہ۔ لیکن وہ زیادہ چمکتا تھا چودھویں کے چاند کی طرح اور میں چھوٹے سے مدھم ستارے کی طرح اس کے آس پاس گھومتا رہتا۔
ذہانت میں وہ مجھ سے بڑھ کر تھا اور طاقت میں، میں۔سیپارہ پہلے ختم کر لینے اور جماعت میں پہلا انعام لینے پہ ہر بار وہ مجھ سے پٹ جاتا، لیکن پھر بھی ہم اکٹھے ہی رہتے۔ وہ گود کا کیڑا تھا، مسجد میں مولوی صاحب کی گود، ہمارے گھر ماں کی گود، چوبارے میں اپنی ماں کی گود، اسکول میں ماسٹر جی کی گود، کینگرو کی اولاد۔ وہ سب کا لاڈلا تھا۔ ہر کوئی اسے پیار کرتا۔ سب اس کا ماتھا چومتے، ابا کے ماتھے کی شکنیں اس کے آنے سے ماند پڑجاتیں۔ اسے اتنا پیار ملتا، تو میں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کے نقص نکالتا۔ پھر مجھے اپنا رنگ کالا، ناک گینڈے جیسا، کان ہاتھی کی طرح، سر لمبوترا، جسم چھوٹا سا اور ٹانگیں ترچھی نظر آتیں، اتنی ڈراؤنی شکل دیکھ کے صابن،ہاتھوں، بازوؤں اور چہرے پر لگائے جاتا تب ماں کا جوتا اْڑتا ہوا آتا اور شیشے میں نظر آنے والا جن دروازے سے باہر جا رکتا۔
اکثر وہ بھی باہر نکل رہا ہوتا، اس کی دلکش مسکراہٹ سے میری حسد کی آگ ٹھنڈی پڑ جاتی اور ہم بانہوں میں بانہیں ڈالے چل پڑتے۔ گلی کی نکڑ سے پیچھے دیکھتا، تو اس کی ماں دروازے کی اوٹ سے کچھ پڑھ کر پھونک رہی ہوتی۔ چوپال کے پاس گزرتے ہوئے جب لوگ ہمیں ببلو اورببلی کہہ کر چھیڑتے، تو میں سوچتا کہ یہ مجھے ببلو اور اسے ببلی کیوں کہتے ہیں، میں یہ سن کر غصے سے سرخ ہوجاتا، لیکن وہ پھر بھی ہنستا رہتا۔ بڑی توند والا رحیما کئی بار میرے پتھر سے بچا اور ہر بار وہ مجھے پکڑ نہ پاتا۔ پھر زیدی اس کے ہاتھ آجاتا اور میں دور کھڑے ہو کر گالیاں دیتا۔ یہ تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ وہ جان بوجھ کر مجھے پکڑنے کے بجائے اسے پکڑتا تھا۔ وہ بڑے عجیب طریقے سے اسے بانہوں میں جکڑ لیتا اور کہتا آجا ببلو چھڑالے اپنی ببلی۔ اور میری گالیوں کی شدت میں اور تیزی آجاتی۔ سارے گاؤں کی گلیاں گھوم پھر کر جب ہم شام کو واپس آتے، تو اس کی ماں ہمیشہ دروازے ہی میں کھڑی ملتی، وہ اْسے اٹھا کر ایسے چومنے لگتی جیسے کوئی گم شدہ بچہ مل گیا ہو۔ میں دل ہی دل میں کہتا، بلی کا بچہ۔ بڑا دل کرتاکہ میری ماں بھی کسی دن دروازے میں کھڑی ہو اور آتے ہی مجھے بانہوں میں اٹھا کر چومنا شروع کردے لیکن ایسا کبھی نہ ہوا، کئی بار میں گھنٹوں گلی میں بیٹھا رہتا پھر اندھیرے سے ڈر کر خود ہی اندر آجاتا۔ ہوتا تو گھر میں بھی اندھیرا ہی تھا لیکن ماں کے پیار کی روشنی سے سارے خوف دور بھاگ جاتے۔ ماں کی مسکراہٹ کی ٹھنڈک سے حسد کی تپش ختم ہوجاتی۔ ماں چولھے کے پاس ہی بٹھا لیتی اور پیار سے مکھن اور دودھ کی بالائی سے کھانا کھلاتی۔
جب زیدی کی چھوٹی سی سائیکل آئی،تو میں اس سے بھی زیادہ خوش تھا، اس نے پہلے ہی دن سائیکل چلانا سیکھ لی اور میں پورا مہینا اوپر بیٹھنے ہی سے ڈرتا رہا۔ وہ خود مجھے سائیکل پہ بٹھاتا اور ساتھ ساتھ سائیکل پکڑے سارا گاؤں گھما دیتا۔ پھر وہ مجھے پیچھے بٹھا لیتا اور ہم گاؤں کی نہر تک سیر کر آتے۔ نہر پہ جانے سے ہر کوئی ڈرتا تھا، میں پیچھے بیٹھا آیت الکرسی پڑھتا اور وہ بڑے اطمینان سے پل کی دوسری طرف جا کر برگد کا چکر لگا کر واپس ہوجاتا۔ ایک دن ماں کو پتا چلا، تو اس نے ابا کو بتا دیا۔ ابا نے عورت کی آدھی گواہی کو سب کچھ مانا اور پلنگ کے نیچے سے بید نکال کے بغیر بولے ہی سب کچھ سمجھا دیا۔ میرا خیال تھا میری چیخ پکار کے بعد چوبارے سے بھی کوئی ملتی جلتی آواز آئے گی، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔صبح میں مار بھول چکا تھا لیکن زیدی جوہڑ سے آگے سائیکل نہیں لے کر گیا۔ پھر جوہڑ ہی ہماری سرحد تھی۔ اس کے پار جاتے ہوئے ٹانگوں میں جان ہی نہ رہتی، سائیکل جیسے رک ہی جاتی۔ اب تک مجھے بھی سائیکل چلانی آگئی تھی، جوہڑ پہ ہم باری بدل لیتے۔ مجھے بڑا غصہ آتا کہ میں تو پیچھے بیٹھ کر سارے گاؤں کی رنگا رنگ کہانیاں سناتا ہوں لیکن زیدی کی چْپ ہی ختم نہیں ہوتی۔ پھر سائیکل گر جاتی، میں اسے اٹھانے کے بجائے سائیکل اٹھا کے بھگا لیتا اور وہ پیچھے پیچھے دوڑتا۔ ایک دن ٹِبیّ سے واپسی پر جہاں سائیکل خود نیچے کو اترتی تھی، میں نے چلتی سائیکل سے چھلانگ لگا دی وہ پیچھے بیٹھا تھا نہ اتر سکا، نہ روک سکا۔ کافی دور جاکے گرا تو اس کا سر پھٹ گیا۔ تب پہلی بار مجھے اْس پہ بہت ترس آیا۔ میں نے آگے بڑھ کر سائیکل اٹھائی، وہ خاموشی سے پیچھے بیٹھا اور ہم حکیم نذیرکی دْکان پہ پہنچ گئے۔ وہ بوسیدہ سے برآمدے میں بیٹھے سرخ ڈاڑھی میں کنگھی کر رہے تھے۔ دیکھتے ہی بولے، چوٹ تو زیدی کو لگی ہے، توکیوں روتا ہے گلزار؟تب مجھے پتا چلا کہ میں رو بھی رہا ہوں۔ زیدی کی پٹی ہوئی اور وہ قمیص سے میرے آنسو صاف کرنے لگا۔ آج خالہ زبیدہ اور بھی شدت سے زیدی کو چوم رہی تھیں۔ پتا نہیں کیوں میرا دل چاہتا تھا کہ خالہ زبیدہ ایسے ہی بید کی چھڑی سے مجھے سمجھائیں جیسے ابا اکثر سمجھاتے تھے، لیکن مجھے روتا دیکھ کر انھوں نے مجھے بھی چْپ کروانا شروع کردیا اور میں گھر چلا آیا۔
اسکول میں ہم دونوں پہلی صف میں بیٹھتے تھے، وہ کونے پر بیٹھا ہوتا لیکن میں اسے گھسیٹ کر دوسرے نمبر پہ کردیتا اور خود اس کی جگہ بیٹھ جاتا۔ میرا خیال تھا وہ پہلے نمبر پہ بیٹھتا ہے اس لیے ہر دفعہ پہلا انعام لیتا ہے اور اگرمیں اْس کی جگہ بیٹھوں گا ،تو میرا پہلا نمبر پکا۔ میں پہلے نمبر پہ آنے کے کئی منصوبے بناتا لیکن اکتیس مارچ کو یہی سوچتا کہ کاش زیدی ہوتا ہی نہ۔ماسٹر جی اس سے بڑا پیار کرتے، اسکول جاتے ہوئے اس کی انگلی پکڑ لیتے اور میں بکری کے بچے کی طرح پیچھے پیچھے چلتا۔ سوال سمجھا کر سب سے پہلے اْسی سے پوچھتے اور ساتھ میں بھی سر ہلادیتا۔ تفریح کے وقت اسے پاس ہی بٹھالیتے۔ وہ زیادہ ہی معصوم تھا، شروع میں لڑکے اسے بہت تنگ کرتے لیکن پھر ماسٹر جی کے ڈر سے ہر کوئی زیدی بھائی کہتا پھرتا۔ مجھے کہیں نہ کہیں سے ببلو اور ببلی کی آواز آہی جاتی۔ایک بار زیدی کو بخار ہوگیا۔ ماسٹر جی، حکیم صاحب کو لے کر گھر آئے اور خود دروازے پر کھڑے رہے، میں پاس کھڑا سہما سہما انھیں ایسے دیکھتا جیسے بجلی کے گیلے کھمبے کے پاس کھڑا ہوں اور چھولیا تو جان سے گیا۔
زیدی کا گھر گاؤں کے اچھے گھروں میں شمار ہوتا تھا۔ زمینیں تھیں، پنشن تھی، گھر میں خوب پیسے کی ریل پیل تھی۔ اس کے ابا کو سب لوگ چچا کہتے تھے۔وہ ایک دن کھیتوں میں کام کرتے سانپ کے ڈسنے سے چل بسے۔ ہنستے بستے گھر میں صفِ ماتم بچھ گئی۔ کفن دفن سے فارغ ہوتے ہی خالہ ہر چیز سے فارغ ہوگئی۔ زمینیں دیورلے گئے۔ مکان نندیں لینے کو تھیں لیکن رو دھو کر کچھ نہ کچھ بچ ہی گیا اور پنشن۔
خالہ زبیدہ سمجھدار خاتون تھیں عدت پوری ہوتے ہی انھوں نے جمع پونجی سے دونوں بیٹیوں کی شادی کا انتظام کردیا، بہنیں رخصت ہوئیں، تو پہلی بار میں نے زیدی کو روتے دیکھا، اسے لپٹ لپٹ کر روتے دیکھ کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آگئے۔
شادیاں بڑی خوش اسلوبی سے ہوگئیں۔ شادی کے تیسرے دن ہم اسکول کے لیے نکلے ،تو گلی کے موڑ سے گھنگھروؤں کی آوازیں آنے لگیں، چندا اپنے گروہ کے ساتھ ناچتے ہوئے گلی میں داخل ہورہی تھی۔ ماسٹر جی ابھی تک نہیں آئے تھے۔ ہم ایک دوسرے کے گلے میں بانہیں ڈالے منہ سے کان لگائے ان کے گھنگھرؤوں کی طرف اشارے کرتے کھڑے ہوگئے۔ وہ خالہ زبیدہ کے گھر کے آگے ناچنے لگے۔ شادی والے گھر سے یہ لوگ وداعی لینے آتے تھے اور تب تک ناچتے رہتے جب تک گھر والے کچھ دے نہ دیتے۔ ہم انھیں دیکھ دیکھ کر ہنس رہے تھے کہ خالہ نے فوراً کچھ پھل ، پیسے اور کپڑے دروازے کی اوٹ سے چندا کو پکڑا دیے۔ وہ واپس جانے لگے،تو ہمارے پاس آ رْکے۔ وہ بڑی عجیب نظروں سے زیدی کو دیکھنے لگی پھر اس نے تالی بجاتے ہوئے کہا’’اوئے کاکا،ہیجڑوں کے پاس کھڑے ہو کے کھسر پھسر کرنا اچھا نہیں ہوتا۔‘‘ اس کی بات مجھے اتنی بْری لگی کہ میں نے پتھر اْٹھالیا لیکن وہ ہمارے ارد گرد جمع ہوگئے، میں نے زیدی کو کھینچا اور اسکول کی طرف دوڑ لگادی۔ تب پہلے دن پتا چلا کہ ہم ماسٹر جی کے بغیر بھی اسکول پہنچ سکتے ہیں۔
صبح اتوار کی چھٹی تھی۔ تالیوں کی آواز سے میری آنکھ کھلی، گلی میں بہت شور تھا، باہر دیکھا ،تو ہر طرف عجیب و غریب لوگ کھڑے تھے، وہ ہر بات پہ تالی ضرور بجاتے۔ پتا نہیں چلتا تھا، یہ مرد ہیں یا عورتیں۔ اچانک میری نظر چندا پہ پڑی وہ خالہ زبیدہ کے دروازے کے آگے جھولی پھیلائے بیٹھی تھی اور اس طرح کے کچھ لوگ گھنگرو باندھے ناچ رہے تھے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کل وداعی لے گئے تھے، توآج اتنے زیادہ کیوں آگئے۔ عورتیں چھتوں پہ کھڑی انگلیاں رکھے پتا نہیں کیا باتیں کر رہی تھیں۔ پوری گلی میں ایسے ہی لوگ تھے، جیسے پورا محلہ ہی ان کا ہے اور پوری دنیا پہ ان کا قبضہ ہے اور مزید ایک گھر پہ اپنا جھنڈا گاڑنے آئے ہیں۔میں سر کھجاتا ان کے درمیان سے گزر کر گلی کے موڑ پہ گیا،تو کچھ لوگوں کے جھرمٹ میں رحیما کھڑا تھا۔ وہ تو جیسے میرا ہی منتظر تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی باچھیں کھل گئیں۔ ’’ببلو بچا لے اپنی ببلی کو، یہ لینے آئے ہیں اسے تیسری دنیا کے لوگ۔ تو بھی چلا جا اس کے ساتھ۔ نہ وہ مرد نہ عورت ‘‘وہ بیہودہ طریقے سے قہقہے لگانے لگا۔ اس کی باتوں سے میں پتھر کا ہوگیا اور ہاتھ میں پکڑا پتھر، پتھر کے انسانوں سے ٹکرائے بغیر زمین پہ جاگرا۔ شاید میں بزدل تھا، زیدی کی ڈھال میں بہادر بنا پھرتا تھا۔
پہلی بار میں اکیلا ہی اسکول گیا۔ نہ زیدی ، نہ ماسٹر جی۔اسکول پہنچتے ہی آوازآ ئی۔
گلزار ہے133ہیجڑے کا یار ہے۔
گلزار ہے133ہیجڑے کا یار ہے۔
سارے لڑکے نعرے لگا رہے تھے جیسے دْونی کا پہاڑا پڑھ رہے ہوں۔ ایک پاؤں پہ وزن ڈال کر آگے کو جھکتے، میری طرف اشارہ کرتے نعرہ لگاتے اور پھر اکٹھے ہنسنے لگتے۔ ایسے لگتا جیسے کئی رحیمے اکٹھے ہوگئے ہوں۔ اور پتھر انسان سے ٹکرانے سے گھبراتا ہو۔
آج ماسٹر جی کچھ زیادہ ہی خاموش تھے، بیٹھے بیٹھے ان کی آنکھوں کی جھیل بھر سی جاتی۔ پھر جھیل سے رومال بھگو کر عینک کے شیشے رگڑے جاتے، بالکل ایسے ہی جیسے زیدی گلاس سے کپڑا بھگو کر سائیکل کے شیشے صاف کرتا۔تفریح کے وقت ماسٹر جی اکیلے ہی بیٹھے رہے۔ آج ان کے پاس کوئی بھی سلیٹ، سلیٹی پکڑے نہیں بیٹھا تھا۔ میرا بڑا دل چاہاکہ وہ مجھے بلا کر پاس بٹھا لیں لیکن وہ آنکھوں کی جھیل سے کپڑا بھگوئے شیشے رگڑ رہے تھے۔گراؤنڈ میں گیا ،تو ایک لڑکا مجھے دیکھتے ہی اونچی آواز میں بولا۔گلزار ہے133لیکن ماسٹر جی کے ڈر سے کسی نے اس کا نعرہ مکمل نہ کیا۔
میرا دل چاہتا تھا کہ یہ نعرہ پورا سنوں، دونی کا پہاڑا پھر شروع ہوجائے۔ لیکن کوئی نہیں بولا۔
اگلی صبح اسکول جانے کے لیے نکلا،تو خالہ زبیدہ کا دروازہ بند تھا، ماسٹر جی بھی دور دور تک نہیں تھے، پاس ہی شہتوت کی ایک سوکھی ٹہنی پڑی تھی۔ مجھے لگا جیسے میں بھی کسی درخت کی سوکھی ٹہنی ہوں، بے کار، فضول، صرف ایندھن۔ پھر ٹہنی اٹھائی اور مٹی پہ لکیر بناتا چل دیا۔نکڑ پہ توند والا رحیما کھڑا تھا، شاید اسے مجھ سے یازیدی سے کوئی بیر تھا، دیکھتے ہی گردن ٹیڑھی کرتے ہوئے بولا۔ لے جائیں گے آج تیری ببلی کو بچالے اسے ورنہ اکیلا رہ جائے گا۔ میں نے پاس پڑا پتھر اٹھانا چاہا لیکن چاہتے ہوئے بھی نہ اٹھا سکا۔ میں بڑے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے چل رہا تھا کہ اچانک کسی بدبو کے پہاڑ سے ٹکرا گیا، جیسے کوڑے کے ڈھیر میں سر آگیا ہو۔ وہ چندا تھی، تالی بجاتے ہوئے کہنے لگی اندھے ہو اور اس کے سارے چیلے کچھ بڑبڑانے لگے، میں منہ اْٹھائے اسے دیکھتا رہا، اس نے سوکھی ٹہنی میرے ہاتھ سے چھینی اور ایک طرف دھکا دے کے چل پڑی۔گلزار ہے133ہیجڑے کا یار ہے
اسکول پہنچتے ہی دونوں طرف لڑکوں کی قطار بن گئی۔ جیسے میرا استقبال ہورہا ہو، جیسے سب مجھ پہ پھول پھینک رہے ہوں۔ دونی کا پہاڑا شروع ہوگیا اورمیں قمیص کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، گردن جھکائے کمرے تک پہنچ گیا۔پتا نہیں کب ماسٹر جی آئے۔گلزار ،آج پیچھے کیوں بیٹھے ہو؟
میں نے بڑی حیرانی سے اِدھر اْدھر دیکھا۔میں سب سے پیچھے دیوار سے لگا بیٹھا تھا۔اپنی جگہ پہ آؤ۔ ماسٹر جی نے رومال سے عینک رگڑتے ہوئے کہا۔میں زیدی کی جگہ چھوڑ کر بیٹھ گیا۔پھر ماسٹر جی جھیل کنارے بیٹھ گئے اور میں بھیگے صفحے بدلتا رہا، ماسٹر جی شیشے رگڑتے اور مجھے کوئی دیکھتا، تو میں کتاب میں منہ چھپا لیتا۔
تفریح ہوئی،تو میں نان ٹکی والے جھونپڑے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔اندر کوئی بات ہورہی تھی۔شروع ہی سے ایسے ہورہا ہے، وہ ہیجڑے کو لے جاتے ہیں۔ نہیں چھوڑتے۔دوسرا شخص بولا۔ تو جس ماں نے جنا، پالا پوسا ہے اس کا کوئی حق نہیں؟
کیا کرے گی وہ گھر میں رکھ کے، ناچنا توسکھا نہیں سکتی، کب تک رکھے گی وہ سوکھی ٹہنی۔پھر دوسرا بولا۔ لیکن یار انھیں پتا کیسے چلا کہ ان جیسا یہاں بھی رہتا ہے۔اس کی بہنوں کی شادی تھی نا، اور یہ لوگ بھی آئے تھے، بس دیکھ لیا انھوں نے۔ یہ پہچان لیتے ہیں اپنی برادری کو دور ہی سے۔
ویسے بڑا ظلم کیا چودھری نے، اپنا ہی بھتیجا ہیجڑوں کو دے دیا۔ چچا زندہ ہوتا، تو کسی کو جرآت نہیں ہونی تھی اس گھر کی طرف آنکھ بھی اٹھانے کی۔ ماں بچاری روتی رہ گئی اور سارے محلے کی عورتیں ایسے رو رہی تھیں جیسے کسی نے ان کا اپنا بیٹا چھین لیا ہو اور زیدی تو بے ہوش ہی ہوگیا تھا۔میں کتاب میں منہ چھپائے کلاس کی طرف چلا آیا اور ماسٹر جی کے پاس جھیل کنارے بیٹھ گیا۔
کیا کوئی ناچنے کے لیے بھی دنیا میں آتا ہے، یہ کیا بات ہوئی کہ ساری عمر ناچتے ہی رہو۔ شاید یہاں ہر کوئی ناچ رہا ہے، کوئی پیسے کے لیے، کوئی شہرت کے لیے، کوئی نام بنانے کے لیے، کوئی نوکری کے لیے، کوئی ترقی کے لیے اور جسے سب کچھ مل گیا وہ خوشی ہی سے ناچے جا رہا ہے۔ بس طریقے جدا جدا ہیں اور بدنام گھنگھرو والے۔
خالہ زبیدہ کو تیز بخار تھا۔ ماسٹر جی، حکیم صاحب کو لے آئے۔ آج حکیم صاحب کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئیں تھیں۔ جیسے خوب روئے ہوں۔ آج ماسٹر جی اندر آگئے۔ گیلا رومال آنکھوں کی آبشار روکنے کی کوشش میں تھا لیکن جو پانی دل میں بنے دکھوں کے ذخیرے سے آتا ہو اسے کپڑے کا ٹکڑا کیسے روک سکتا ہے۔
گلزار بیٹا یہ تین پْڑیاں دو دو گھنٹے بعد کھلا دینا اور پانی کی پٹیاں کرتے رہنا۔ یہ کہتے کہتے رومال حکیم صاحب کی آنکھوں تک چلا گیا۔ خالہ زبیدہ کا ماتھا آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ غنکھیں انگاروں کی طرح سرخ۔ کھدر کی ٹھنڈی پٹی، آگ میں پڑے لوہے کی طرح گرم ہوجاتی۔ میں پٹیاں بدلتا رہا لیکن آگ بڑھتی گئی۔مجھے ایسے لگا جیسے خالہ زبیدہ ہی میری ماں ہے اور میں شروع سے چوبارے میں رہتا ہوں اور ٹھنڈی پٹیاں کرنا میرا ہی کام ہے۔وہ کچھ بول رہی تھیں۔
ظالموں کو خود ہی میرا اللہ پوچھے گا۔ ماں کو بیٹے سے جدا کردیا۔ کیسے رہے گا وہ میرے بغیر۔پتا نہیں کچھ کھایا بھی ہوگا اس نے۔ پتا نہیں سویا بھی ہوگا کہ نہیں۔
تو کیوں روتا ہے گلزار! انھوں نے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی۔
میں نے بازو سے اپنے آنسو صاف کیے اور ہاتھوں سے بہتی آبشار روکنے لگا۔ گرم پانی، اْبلتا ہوا۔ وہ کہتا تھا ماں میں تجھے حج کراؤں گا۔ کہتا تھا جب پڑھ لکھ کہ بڑا افسر بن جاؤں گا ،تو شہر میں کوٹھی ہوگی اپنی۔ شہر کی طرح اپنے گاؤں کی گلیاں بھی پکی کرا دوں گا۔ ماں کتنا کیچڑ ہوتا ہے نابرسات میں۔ گاڑی میں گھومیں گے اور بہنوں کے پاس بھی اپنی گاڑی پہ جائیں گے۔ گلزار بڑی مشکل سے گاڑی چلانا سیکھے گا۔ کہتا تھاماں مجھے یہ ستارے ہلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اپنے جہاز پہ جاؤں گا انھیں دیکھنے۔ وہ آنسوؤں میں بھیگے الفاظ کہتی گئیں۔کیوں روتا ہے گلزار۔ کانپتے ہوئے گرم ہاتھ میرے آنسو صاف کرنے لگے۔
ٹھنڈی پٹیوں سے دل کے پھوڑے پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ غم کی تپش برف سے کم نہ ہوئی۔ کہنے لگیں سو جاؤ بیٹا کچھ نہیں ہوتا۔
ساری رات کروٹیں بدلتا رہا۔ اذان کے ساتھ اٹھتے ہی میں نے خالہ کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا۔ برف کی طرح ٹھنڈا۔ بخار چلا گیا، لیکن جاتے جاتے سانس بھی ساتھ لے گیا تھا۔ میں نے ہاتھوں سے ان کی آنکھیں بند کیں اور اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں پھوٹ پڑیں۔ اب کوئی گرم ہاتھ آنسو صاف کرنے نہ آیا۔ ایسے محسوس ہوا جیسے خالہ زبیدہ نہیں بلکہ میری ماں ہی دنیا چھوڑ گئی۔
ماں اپنے بیٹے سے ایک رات بھی جدا نہ رہ سکی۔ میں نے چوبارے سے ماں کو بلانا چاہا، منہ سے صرف یہی نکلا ماں! اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اونچی آواز میں۔ جیسے ابا نے بانس پکڑا ہو اور میں بچنے کے لیے آہ وبکا کررہا ہوں۔ پھر پوری گلی میں بین شروع ہوگیا۔
امتحان نزدیک تھے اب سارا دن اسکول میں گزر جاتا۔ آتے ہوئے شام ہوجاتی اور ماں کھانا کھلا کر سلا دیتی۔ پرچے ہوئے اور اکتیس مارچ بھی آگئی۔ اس دن میں اور زیدی عید کے کپڑے پہن کر گھر سے نکلتے، بھاگتے، رکتے، چلتے، گردن میں بانہیں ڈالے اسکول پہنچ جاتے۔ لیکن اس بار میں اور شہتوت کی سوکھی ٹہنی، مٹی پہ لکیر بناتے اسکول پہنچ گئے۔
مجھے پہلا اِنعام دیتے ہوئے ماسٹر جی کے ہاتھ کانپے اور پھر وہ عینک رگڑنے لگے، لیکن کانپتے ہاتھ عینک نہ سنبھال سکے اور وہ گرِ کر ریزہ ریزہ ہو گئی۔ بالکل ان کے دل کی طرح۔
میرا بڑا دل کرتا تھا کہ پہلے نمبر پر آؤں لیکن آج مجھے کوئی خوشی نہ ہوئی۔ ہر سال دوسرا اِنعام ملتا،تو اسکول ہی میں کھول لیتا لیکن اس بار چمکتے کاغذ کو ہاتھ لگانے کو بھی دل نہ کیا۔ ماسٹر جی کی عینک ٹوٹ گئی تھی۔ انھوں نے ایک ہاتھ میں سوکھی ٹہنی پکڑی اور دوسرا ہاتھ مجھے دیا۔ وہ بار بار رْک کر اپنی جھیل جیسی آنکھوں میں رومال بھگوتے لیکن عینک رگڑ کے ڈر سے ٹوٹ چکی تھی۔ رکنے سے ٹہنی کی لکیر ٹوٹ جاتی، تب ان کی باتیں دل کی لکیر جوڑنے کی کوشش کرتیں۔ رومال بھگوتے ہوئے کہنے لگتے، اگر کسی میں خامی ہو تو اسے گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیتے ہیں! اگر اس میں کوئی کمی تھی تو اللہ نے خوبیاں بھی بے شمار رکھی تھیں، کیوں ہم اسے وہاں پہنچنے سے روک نہ سکے؟ اتنے قابل بچے کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں۔ وہ پڑھ لکھ کے دنیا کا قابل ترین انسان بن سکتا تھا، لیکن ہم نے اسے آگ میں جھونک دیا۔ کیوں نہیں ہم اس قابل ہوئے کہ اسے لے آئیں پھر کتابوں والی، خوشیوں والی، اپنوں والی زندگی میں۔
میرا بڑا دل کرتا تھا کہ زیدی کی طرح کبھی میں بھی ماسٹر جی کی انگلی پکڑ کے جاؤں لیکن آج میں دور بھاگنا چاہتا تھا، بہت دور۔
ماسٹر جی کو گھر چھوڑ کر میں سیدھا چندا کے گھر کی طرف چل دیا۔ وہ جوہڑ کے پاس تھا، گاؤں کے باہر۔ چندا مجھے اندر ہی لے گئی، صحن میں کھڑے ہو کر اس نے آواز دی۔ ببلی۔ دیکھ باہر کون آیا ہے اس کے منہ سے زیدی کا اْلٹا نام سن کے میں پتھر ڈھونڈ رہا تھا کہ زیدی مجھے کھینچ کر باہر لے آیا۔ کیوں آیا یہاں، گندی جگہ ہے یہ۔ اور وہ رونے لگا۔
میں نے چمکتے کاغذ میں بند پہلا انعام اسے تھما یا اور چپکے سے واپس چل دیا۔گلزار رْک۔ ایک مانوس سی آواز آئی۔وہ سرخ امرود کی ٹوکری پکڑا کر کہنے لگا۔ جاتے جاتے ہی کھا لینا۔سرخ امرود صرف چندا کے گھر ہی لگتے تھے، گاؤں میں کوئی نہیں کھاتا تھا۔ لوگ کہتے تھے جس نے چندا کے سرخ امرود کھالیے وہ نامکمل ہوجائے گا۔ اس کے امرود فقیر کھاتے تھے یا اجنبی۔ گاؤں پہنچا تو چوپال کے آگے رحیما بیٹھا تھا۔ وہ بولے بنا نہ رہ سکا۔لے آیا اپنی ببلی کے امرود۔ اس نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔میں نے ایک امرود پکڑ کر پورے زور سے مارا۔ وہ آنکھ پکڑ کے بیٹھ گیا۔ آج نہ میں بھاگا اور نہ اس نے کسی کو پکڑا۔
چوبارہ خالی ہوگیا۔ ابا نے بانس نکالنا چھوڑ دیا۔ زیدی کی سائیکل ہمارے جامن کے نیچے کھڑی تھی، زنگ آلود، مٹی سے بھری۔ جب کبھی ماں اسے اِدھر اْدھر کرتی وہ چیخنے لگتی، کراہتے ہوئے بیمار کی طرح۔ شاید بچھڑے ہوئے اپنوں کی یاد میں۔
ماسٹر جی دیر سے اسکول آنے لگے، دونی کے پہاڑے کے بعد۔ عینک رگڑنے سے دھیان ہٹتا،تو کبھی کبھی مجھے اگلی صف میں بیٹھنے کا کہہ دیتے۔ عینک ریزہ ریزہ ہوتی ہی رہتی، پھر میں اور شہتوت کی سوکھی ٹہنی ماسٹر جی کو پکڑے گھر چھوڑ آتے۔ جہاں ٹہنی کی لکیر ٹوٹتی وہاں ماسٹر جی کی باتیں ایک اور لکیر بنا دیتیں۔
ہر اکتیس مارچ کو چمکیلے کاغذ میں لپٹی کوئی چیز زیدی کو مل جاتی اور واپسی پہ میرے ہاتھ میں سرخ امرودں کی ٹوکری ہوتی۔ رحیما چھت سے گر کر اپنی زبان کٹوا بیٹھا تھا، وہ چوپال کے آگے بیٹھا ہوتا۔ جاتے جاتے کچھ امرود میں اس کی جھولی میں ڈال دیتا اور وہ ہر بار کچھ کہنے کی ناکام کوشش کرتا۔
دسویں کے بعد ماسٹر جی شہر جا کر مجھے کالج میں داخل کروا آئے۔ ابا جی ریٹائر ہوگئے لیکن سائیکل کو دوسری سواری مل گئی۔ باپ کے بعد بیٹا۔ یہ ابا کا رازدار تھا سارے راستے مجھے ان کی کہانیاں سناتا اور میں کالج پہنچ جاتا۔ کالج میں کوئی دونی کے پہاڑے والا نہ تھا، لیکن مجھے ایسا ہی لگتا جیسے یہاں سب مجھے جانتے ہیں۔ سب سے پچھلی کرسی میری ہوتی، چاہے سارا کمرا خالی ہو۔
شاید میں صرف زیدی ہی کو دوست بناناجانتا تھا یا زیدی نے مجھے دوست بنایا تھا، اس کے بعد میرا کوئی دوست نہ بنا۔ چار سال پچھلی کرسی ہی پہ گزر گئے۔ ایم ۔اے میں تو لڑکیاں بھی ساتھ آگئیں۔ پھر ساری جماعت دو، دو ہوگئی لیکن میں پھر بھی اکیلا ہی رہا۔
گاؤں کے اسکول میں ہیڈ ماسٹر بن کر گیا،تو پہلے دن مجھے اسمبلی میں اِسٹیج پر بلایا گیا۔ سامنے بچوں کی قطاریں تھیں اور چاروں طرف خزاں رسیدہ درخت۔ میرے ہاتھ میں عینک تھی جو آنکھوں کی جھیل میں بھیگے رومال سے رگڑ کھارہی تھی، پھر وہ میرے پاؤں پڑی اور ریزہ ریزہ ہوگئی۔ کسی نے شہتوت کی سوکھی ٹہنی میرے ہاتھ میں دی اور میں مٹی پہ لکیر بناتا دفتر پہنچ گیا۔ اسی طرح ایک دن میں گھر پہنچا،تو ماں نے میرا ہاتھ کسی کے آگے کردیا، انگوٹھی نے مجھے جکڑ لیا، ماں کو مبارک، خیر مبارک ہونے لگی۔
کئی سال بعد بھی میں گھر سے نکلتا ،تو زبیدہ خالہ کے گھر کی طرف نگاہ ضرور جاتی، لیکن اب زیدی نہ نکلتا۔ وہاں چودھری بیٹھا دونوں ہاتھ سر پہ رکھے دیمک زدہ دروازے کو دیکھتا رہتا۔ لوگ کہتے تھے
جوان بیٹے کی موت نے اسے پاگل کر دیاہے۔چوبارہ تب سے خالی پڑا تھا، لوگ جھگی میں رہنا منظور کرلیتے تھے لیکن چوبارے میں کوئی رات بھی گزارنے کو تیار نہ تھا۔ کسی نے مشہور کردیا تھا، جو یہاں رہے گا اس کی اولاد نامکمل ہوگی۔ جیسے زیدی۔
برسات کے دن تھے۔ بارش جم کے برس رہی تھی، شاید گاؤں سے برسوں پرانا کوئی انتقام لینے آئی ہو۔ میں گلی میں بکھری اپنی دیوار کی اینٹیں اکٹھی کررہا تھا کہ گاؤں کا پٹواری آگیا۔ اس نے چمکیلے کاغذ میں لپٹی کوئی چیز دی اور چلا گیا۔ یہ چوبارے کی رجسٹری تھی اور ساتھ ایک صفحے پر یہ الفاظ۔
گلزار! ماں تجھے بھی اپنا بیٹا سمجھتی تھی۔ اگر ایک بیٹا وہاں رہنے کے قابل نہیں،تو دوسرا تو ہے نا۔ ماں کا گھر اجڑنے نہ دینا۔ مجھے پتا ہے تیری دیوار گر گئی ہے اور مکان کی حالت بھی نازک ہے۔ تیز بارشوں میں کچے مکان سے یونہی ہوتا ہے۔ اگر تو مجھے اپنا بھائی نہیں تو دوست ہی سمجھ لے اور آج ہی سامان اٹھا کہ چوبارے میں چلاجا۔
چوبارے کا دروازہ کھلتے ہی چودھری چیخنے لگا۔ وہ کیچڑ میں لتھڑا ہوا بھاگا اور بکھری اینٹوں میں گر گیا۔
چوبارہ بالکل ویسا ہی تھا، ایسے جیسے یہاں سے ابھی ابھی کوئی گیا ہو۔ یہاں باہر کی برسات کا کوئی ڈر نہیں تھا، لیکن اندر کی برسات رکنے کا نام نہ لیتی۔ کئی بار میری بیوی پوچھتی کہ آپ رو کیوں رہے ہیں۔ پھر میں بہتے آنسو روکنے کی کوشش کرتا۔ عینک رگڑ کے ڈر سے گرتی اور ریزہ ریزہ ہوجاتی۔
ایک دن میں اسکول سے آیا،تو ماں نے سینے سے لگا لیا۔ تو باپ بنا ہے۔ ماں نے گول مٹول، سرخ رخساروں والا نرم و نازک سا احساس میری بانہوں میں بھر دیا۔ وہ بالکل اس کی طرح تھا، آنکھیں چھلک پڑیں اور اچانک منہ سے نکلا۔ زیدی۔ اور میں نے اسے چوم لیا۔
دروازے پہ گھنگھروؤں کی چھن چھن اور تالیوں کی گونج کا شور اْٹھا۔ پھر دروازہ کھلا کوئی پہچانا سا چہرہ تھا لیکن بدلا ہوا، آنکھوں کی جھیل بھر گئی، عینک کے شیشے رگڑ کے ڈر سے گرے اور شکستہ دل کی طرح بکھر گئے۔ زبان کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن ہونٹ سل گئے۔ میں اس کی بانہوں میں بانہیں ڈالنا چاہتا تھا لیکن اٹھے ہوئے ہاتھ آنکھوں پہ جا
ٹھہرے، آگے بڑھنا چاہتا تھا مگر چلتے قدم رْک گئے۔ لیکن بہتے آنسو نہ رْکے۔
/خ/خ/زیادہ سچا ہے