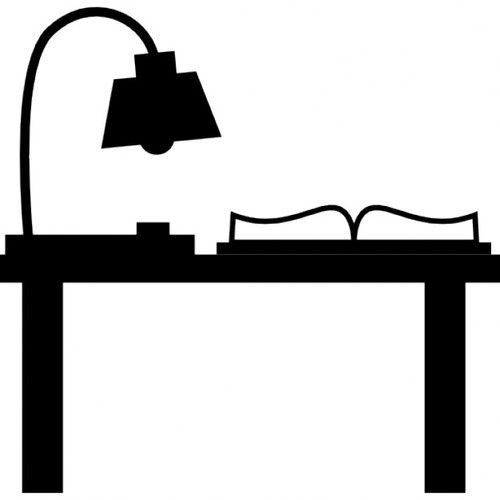لفظوں کی اپنی زندگی ہوتی ہے۔ اس زندگی کے نشیب و فراز ہوتے ہیں۔ اُن میں اپنی قسم کی ڈرامائیت اور ان کا اپنا رومان ہوتا ہے۔ وہ الفاظ جو اوپر سے روکھے پھیکے، کھوکھلے اور رسمی معلوم ہوتے ہیں، ان میں سے بعض کے پیچھے حیرت انگیز کہانیاں، رسم و رواج اور تاریخی حقیقتیں چھپی ہوتی ہیں۔ ان پس پردہ حقیقتوں کی تلاش اور ان کے بارے میں علم سے ہم کو ایک الگ ہی قسم کا لطف آتا ہے، کچھ ایسا ہی جیسے روزن در میں آنکھ لگا کر چوری چھپے کے نظارے میں آتا ہے۔ آئیے لغت کے دفتر میں پڑی درازوں میں آنکھ لگا کر دیکھیں کہ کس لفظ کے آنگن میں کیا ڈراما چل رہا ہے۔
اب سائرن کے لفظ کو ہی لیجیے۔ یہ خشک، غیر شاعرانہ سا نام جس کے بھدے پن کو ہم بعض اوقات ‘‘بھونپو’’ کہہ کر ظاہر کرتے ہیں، آج کی صنعتی زندگی کا حصہ بن گیا ہے۔ بڑے بڑے شہروں کی بھاگم بھاگ اور بھیڑ والی مشینی زندگی کا ایک حصہ وہ فیکٹریاں ہیں جن کی دھواں اگلتی چمنیاں اور ان شہروں کی افقی شناخت بن چکی ہیں۔ انھیں فیکٹریوں سے سائرن کی وہ آوازیں سننے کو ملتی ہیں جن کے ساتھ فیکٹریوں کے آہنی پھاٹک تھکے ہوئے انسانوں کی ایک بھیڑ کو اگل دیتے ہیں اور مزدوروں کی دوسری بھیڑ کو اپنے اندر بند کر لیتے ہیں، لیکن اس غیر شاعرانہ منظر کو حرکت بخشنے والے لفظ ‘‘سائرن’’ کو صدیوں پہلے شاعرانہ تخیل نے جنم دیا تھا۔ قدیم یونانی شاعروں نے ‘‘سائرن’’ کا ایک عجیب پر اسرار مخلوق کی شکل میں تصور کیا تھا۔ ایک ایسی مخلوق کی شکل میں جس کا چہرہ، زلفیں ، گردن اور سینہ حسین عورتوں جیسا اور باقی جسم پرندوں کی طرح ہوتا تھا۔ جب سائرنس گاتیں تو آس پاس کی دنیا ان کے شیریں نغمے میں محو ہو جاتی، لوگ بے قابو ہو جاتے، سمندروں میں چلتے جہاز رک جاتے۔ ملاح سمندر میں کود کر سائرنس کے جزیروں کی طرف مجنونانہ انداز سے تیرنے لگتے اور کنارے پر پہنچ کر چٹانوں پر بیٹھ کر سائرنس کے نغمے سنتے رہتے۔ ان کو تن بدن کا، کھانے پینے کا ہوش نہ رہتا۔ یہاں تک کہ وہ وہیں چٹانوں پر بیٹھے بیٹھے دم توڑ دیتے۔ اس جزیرے سے کوئی زندہ لوٹ کر نہیں آتا، لیکن ایک بار انہونی ہوئی۔ جب یونانی ارگوناٹس کا جہاز بحیرۂ روم میں سائرنس کے جزیرے کے پاس سے گزرا تو ان کے ساتھ دیوتاؤں کا چہیتا موسیقار آفیس بھی تھا۔ آفیس کے کان میں جیسے ہی سائرنس کی آواز پڑی تو اس نے اپنا رباب اٹھایا اور اپنا بہترین نغمہ اپنے سروں میں چھیڑا۔ سائرنس کی آواز دب گئی۔ صرف ایک ایسا بد قسمت ملاح تھا جس پر ان کا جادو چل گیا۔ وہ بے قابو ہو کر سمندر میں کود پڑا اور پھر واپس نہ آیا۔ لیکن سائرنس کو سب سے زیادہ مایوسی اس وقت ہوئی جب یونانی ہیرواوڈے سیس ان کے جزیرے کے پاس سے گزرا ۔ اوڈے سیس نے پہلے ہی اپنے ساتھیوں اور ملاحوں کے کانوں میں موم بھروا دیا تھا۔ لیکن خود اسے یہ اشتیاق تھا کہ وہ یہ سنے کہ سائرنس کیا گاتی ہیں۔ اس لیے اس نے حکم دیا کہ خود اس کو رسیوں سے متول کے ساتھ کس کر باندھ دیا جائے۔ اس نے سنا کہ وہ گا رہی ہیں کہ‘‘ وہ کیا ہے جو انسان کو دائمی سکون دے سکتا ہے اور لافانی خوشی بخش سکتا ہے۔ وہ کیا ہے جسے لافانی حسن کا نظارہ ہو سکتا ہے۔ وہ کیا ہے جو موت کے تصور سے نجات دلا سکتا ہے۔ ان سب کا راز ان کے پاس ہے۔ ان کے ان نغموں میں ہے جو وہ سنانے والی ہیں۔ ان نغموں میں وہ مٹھاس ہے جو کبھی ختم نہ ہو گی۔ وہ لطف ہے جو کبھی کم نہ ہو گا۔ وہ مسرت ہے جس کو کبھی زوال نہیں’’۔ ان نغموں کو سن کر اوڈے سیس بیتابانہ خود کو رسیوں سے آزاد کرانے کے لیے جد و جہد کرتا رہا۔ اس کا جسم لہو لہان ہو گیا۔ اس کی فوق الانسانی طاقت جواب دے گی۔ سائرنس کی آواز کی طلسمی کشش نے اس کے فولادی ارادے کو موم سے بھی زیادہ نرم کر دیا۔ بہرحال اس کی دانشمندی کی وجہ سے اس پر اور اس کے ساتھیوں پر سائرنس کا جادو نہ چل سکا اور وہ سب صحیح سلامت ان کے نغموں کی زد سے باہر نکل گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اوڈے سیس کے اس طرح بچ کر نکل جانے سے سائرنس کو شدید جھنجھلاہٹ ہوئی او رانھوں نے غصے میں آ کر سمندر میں کود کر جان دے دی۔ اس طرح سائرنس کو اس کے ہی خالق یونانی شاعروں نے مار ڈالا ، لیکن انیسویں صدی میں ایک فرانسیسی موسیقار نے انھیں پھر زندہ کیا اور اسی کے فیض سے سائرنس سے ہم آج بھی واقف ہیں۔ ۱۸۱۹ء میں ‘‘کانیاردیلا تور’’ نامی اس موسیقار نے موسیقی کے سر پیدا کرنے اور ان کے ارتعاش کی پیمایش کے لیے ایک آلہ بنایا اس کا نام اس نے سائرن رکھا۔ ظاہر ہے یہ قدیم یونانی شاعروں کے تخیل کو اس کا خراج عقیدت تھا، لیکن دور حاضر نے انسان کے رومانی تخیل کو بار بار صدمہ پہنچایا ہے اور یہی عمل اس نے سائرن کے لفظ کے ساتھ کیا۔ انیسویں صدی کے آخر تک جگہ جگہ فیکٹریاں قائم ہو گئیں اور ان میں یکساں بھرائی ہوئی آواز میں اطلاع دینے والی سیٹیوں کا رواج عام ہوا تو اس کے لیے کسی لفظ کی ضرورت ہوئی اور دیلا تور کے آلے کی مناسبت سے اسے سائرن کہنے لگے۔ سوچیے کہاں وہ دائمی مسرت کی بشارت سنانے والی سائرنس کے نغمے اور کہاں فیکٹری کے بھونپو کی سامعہ خراش ناگوار آواز۔
آئیے ایک اور لفظ ‘‘پمفلٹ’’ کے اتار چڑھاؤ دیکھیں۔ یہ بھی ایک ایسا لفظ ہے جس کی دلچسپی کو ہماری موجودہ میکانکی زندگی نے سوخت کر لیا ہے۔ آج پمفلٹ کسی روکھے سوکھے موضوع پر نظریاتی بحث کرنے والا پروپیگنڈے کی غرض سے چھاپا گیا کتابچہ ہے اور ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ سات آٹھ صدی قبل پمفلٹ کے نام سے لوگوں کے منہ سے کس قسم کی رال ٹپکنے لگی تھی۔ بارھویں صدی میں اٹلی میں پمفلٹ نے ایک نہایت چٹ پٹی کہانی والی نظم کی حیثیت سے جنم لیا تھا۔ اس کہانی کا ہیرو ایک بوڑھا ہوتا تھا جس کو پیم فیلس کا نام دیا گیا۔ پیم فیلس کے لفظی معنی ہر ایک کے شیدائی یا دل پھینک کے ہوتے ہیں۔ یہ نظم ایک ایسے دل پھینک بوڑھے کی رنگ رلیوں کی کہانی تھی جو اپنی مطلب برآری کے لیے طرح طرح کے حیلے کرتا ہے اور انتہائی معزز اور باعفت خواتین کو ساری چوکیداری اور پہروں کے باوجود جُل دینے میں کامیاب ہوتا ہے۔ یہ بدمعاشیوں کی کہانی لوگوں میں بے حد مقبول تھی اور اسے لوگ چھپا چھپا کر پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ اٹلی کی خانقاہوں میں راہب بھی اسے اپنے چغوں میں چھپا کر لے جاتے اور تکیوں میں چھپا کر رکھتے، کیونکہ اس وقت تک چھاپے کا رواج نہیں ہوا تھا۔ اس لیے گنی چنی ہاتھ سے لکھی ہوئی نقلیں ہی لوگوں میں گردش کرتیں۔ اس غرض سے کہ انھیں چھپا کر رکھنے میں آسانی ہو، یہ نقلیں چھوٹے سائز کے کاغذ پر کی جاتیں۔ چھاپے کی ایجاد کے بعد تو اس قسم کے قصوں کہانیوں کی نقلوں کو آسانی کے ساتھ لوگوں تک پہنچایا جانے لگا، لیکن پمفلٹ کا لفظ زندہ رہا اور چھوٹے سائز کی کسی بھی کتاب کو پمفلٹ کہنے لگے۔
اب آئیے ان جوبلی منانے والوں سے پوچھیں کہ یہ جوبلی کیوں مناتے ہیں۔ پہلے تو صرف پچاس سالہ ہی جوبلی منائی جاتی تھی، لیکن اب تو صرف پچیس سالہ پچاس سالہ، ساٹھ سالہ، پچھتر سالہ جوبلیاں ہی نہیں، بلکہ کبھی بھی منائی جانے لگی ہیں۔ دراصل جوبلی یہودیوں کا ایک تہوار ہے جسے وہ پچاس سال میں ایک بار مصر سے اپنے اخراج کی یاد میں منایا کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں عہد عتیق (اولڈ ٹیسٹا منٹ) کی دوسری کتاب میں واضح طور پر احکامات موجود ہیں۔ یہ موقع پوری چھٹی کا موقع ہوتا ہے۔ زمین کو دو سال کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ زمین کو آرام ملے۔ کھیتوں کو جوتا نہیں جاتا۔ باغوں کے پودوں کی چھٹائی نہیں کی جاتی۔ پھل دار درختوں کے پھل نہیں چنے جاتے، زمین سے اپنے آپ نکلنے والے پھلوں کو غریبوں، غلاموں اور اجنبیوں اور مویشیوں کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لوگ مچھلی پکڑ کر، شکار کر کے شہد کی مکھیوں سے حاصل کیے ہوئے شہد اور مویشیوں سے حاصل کیے دودھ دہی وغیرہ پر ہی اپنی گزر بسر کرتے ہیں۔ زمینوں کو ان کے اصل مالکوں کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ اس موقع پر لوگ بگل اور مینڈھے کے سینگوں سے بنے ہارن بجا بجا کر خوشیاں مناتے ہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ و ہ لفظ سے جوبلی نکلا ہے اس کا مطلب ہی مینڈھے کا سینگ ہوتا ہے۔
عیسائیوں نے جوبلی کا لفظ تقریب کے معنی میں اختیار کیا اور کسی واقعے کی پچاسویں سالگرہ کو جوبلی کی حیثیت سے منایا جانے لگا، مثلاً شادی یا تخت نشینی کی اس قسم کی سالگرہ کو گولڈن جوبلی کا نام دیا گیا۔ ملکہ وکٹوریہ نے ۱۸۹۷ء میں اپنی تخت نشینی کی ساٹھویں سالگرہ ڈائمنڈ جوبلی کے طور پر منائی اور اس کے بعد ڈائمنڈ جوبلی کا فیشن ہو گیا۔ ملکہ ورکٹوریہ کے پوتے جارج پنجم نے پچیسویں سال سلور جوبلی منانے کا رواج ڈالا۔ اب تو جوبلیاں کسی وقت منائی جانے لگیں۔ اور ان کا نام پنساری کی دکان کی ہر شے پر پڑ گیا ہے۔ جیسے پہلی سالگرہ کو کاغذ جوبلی، دوسری کو روئی جوبلی، تیسری کو چمڑا جوبلی، چوتھی کو پھل جوبلی اور پانچویں کو لکڑی جوبلی کہنے لگے ہیں۔ ساتویں جوبلی تانبے، آٹھویں جوبلی کانسے، نویں چینی کے سامان ، دسویں ایلومنیم، تیسویں موتی، چالیسویں لعل اور پچھترویں پلاٹینم سے منسلک کر دی گئی ہیں۔
جوبلی کا سینگ سے تعلق ہے، لیکن کیا کبھی آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ شاہ اور بادشاہ کا بھی سینگ سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جس زمانے میں انسان جنگلوں میں گزر بسر کرتا تھا، اس وقت وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے جنگلی جانوروں کو مارا کرتا تھا، لیکن سینگ والے جانوروں کو مارنے کے لیے اسے بڑی ہوشیاری اور پھرتی کی ضرورت ہوتی تھی۔ چنانچہ جب وہ شکار کر لیتا تو جانور کے سینگ اپنے سر پر لگا کر خوشیاں مناتا تھا۔ آج بھی مدھیہ پردیش کے بستر کے علاقے میں رہنے والی قبائلی لوگوں میں سر پر سینگ پہن کر ناچنے کا رواج ہے۔ قدیم ایران میں یہ رواج تھا کہ سردار سر پر سینگ پہنا کرتا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں تاج پہننے کا رواج بھی اسی قسم کی کسی رسم سے پڑا ہو۔ فارسی میں سینگ کو شاخ کہتے ہیں چناچہ سینگ پہن کر بیٹھنے والے سردار کو بھی شاخ کہنے لگے جس نے دھیرے دھیرے ‘‘شاہ’’ کی شکل اختیار کر لی۔
شاخ سے شاخانہ یاد آتا ہے۔ کسی ایسے مسئلے کو جو کسی قسم کے فتنے و فساد کا سبب بنے اسے بعض اوقات شاخسانہ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ بھی سینگ کی ہی کارستانی ہے۔ کیسے؟ شاخسانہ دراصل شاخ خانہ تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ ایران میں ایک قسم کے اڑیل فقیر ایسے بھی ہوتے تھے جو چاہے کچھ ہو جائے، کچھ نہ کچھ لے کر ٹلتے تھے۔ یہ لوگ اپنے ساتھ بکری کا سینگ اور بکری کے شانے کی ہڈی کا ٹکڑا رکھتے تھے او رانھیں رگڑ رگڑ کر ایسی مکروہ آواز پیدا کرتے تھے کہ لوگ ان سے پیچھا چھڑانے کے لیے انھیں جلدی سے کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کر دیا کرتے تھے۔ لیکن اگر کوئی شخص اتنی آسانی سے انھیں پیسا دینے پر راضی نہ ہوتا تو یہ لوگ اس نکیلے سینگ سے خود اپنے جسم کو لہو لہان کر لیتے اور خوب شو و غل مچاتے یہاں تک کہ سامنے والا مجبور ہو کر انھیں کچھ نہ کچھ دے کر ٹالتا۔ اسی بنا پر جب کوئی شخص کسی طرح کی حجت کر کے کوئی فتنہ کھڑا کرتا ہے تو اسے بھی شاخسانہ کہنے لگے۔
دھرنے کا لفظ جو آج کل سیاسی کارگزاریوں کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ اس کے پیچھے کچھ اسی قسم کی اصلیت ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اپنی مانگیں منوانے کے لیے دھرنے پر بیٹھنا جد و جہد آزادی کے دوران مہاتما گاندھی کے عدم تشدد کے حربوں کے طور پر مقبول ہوا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ طریقہ ہندوستان میں بہت زمانے سے رائج ہے۔ اس کی بنیاد اس عقیدے پر ہے کہ مظلوم کی ہائے، ظالم کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اگر مظلوم ظالم کے دروازے پر بیٹھ کر اپنے آپ کو بھوکا رکھ کر اپنے آپ کو ایذا پہنچا کر، اپنے اعضا کو کاٹ کر یا مجروح کر کے تکلیف پہنچائے گا تو اتنی ہی تکلیفیں ظالم کو پہنچیں گی۔ اس کوشش میں اگر مظلوم کی جان چلی جائے تومظلوم کی روح بھوت بن کر ظالم کی زندگی کو عذاب بنا دے گی۔ اس حربے کا اتنا رواج تھا کہ کبھی کبھی قرض دینے والے نادہند قرض داروں کے گھر کے سامنے دھرنے پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ فقیروں کے کچھ گروپوں نے بھی پیسے وصول کرنے کے لیے یہ طریقہ اپنا رکھا تھا۔ ان کے طریقوں کے لحاظ سے ان کے الگ الگ نام تھے۔ ڈوری والے گلے میں ڈوری کس کر پھانسی کی دھمکی دیتے تھے۔ ڈنڈی والے ڈنڈیاں بجا بجا کر دن دن بھر کوستے رہتے تھے۔ اڑی مار دکان کے سامنے اڑ کر کھڑے ہو جاتے اور دن دن بھر کھڑے رہتے۔ دھرنے پر بیٹھنا راجستھان اور گجرات میں بہت عام تھا۔ گاندھی جی نے یقینا اپنے وطن گجرات میں یہ سب کچھ دیکھا ہو گا۔ انھوں نے اس طریقے کو جس سے عام لوگ اچھی طرح واقف تھے، بڑی خوبی کے ساتھ عدم تشدد کے اصول کو اپناتے ہوئے اپنے سیاسی نقطۂ نظر کو ایک طاقتور حکومت پر واضح کرنے کے لیے استعمال کیا۔
لفظوں کی اپنی دنیا ہے۔ ان کی آپ بیتی میں حیرت انگیز موڑ ہیں۔ عجیب عجیب اسرار ہیں۔ انوکھا رومان ہے۔ ان کی زندگی میں تو جھانک کر دیکھیے، ان کی داستان، انسانی زندگی کی داستان سے کچھ کم دلچسپ نہیں۔
٭٭٭